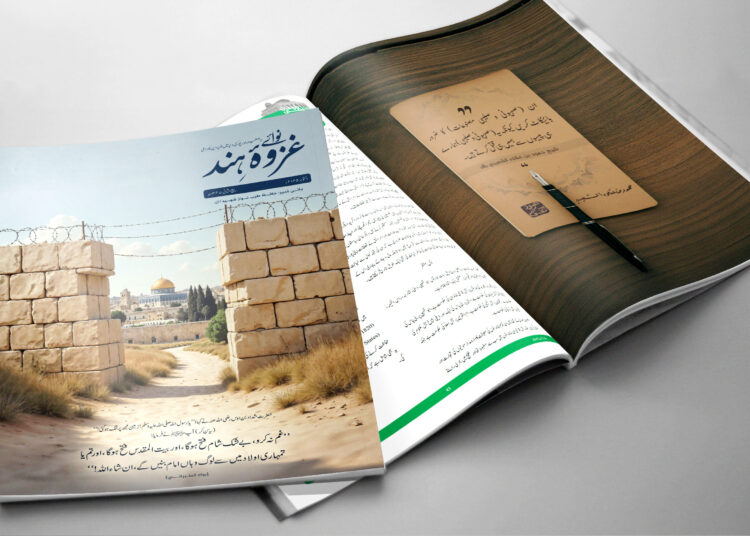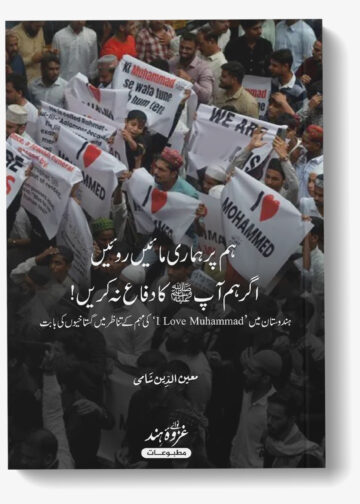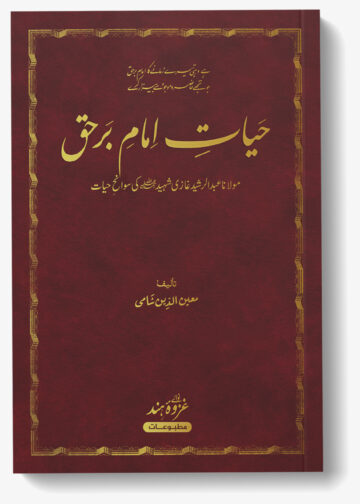مضمونِ ہذا کا مقصد و ہدف اہالیانِ بنگلہ دیش کی شناخت ……بحیثیت ’بنگالی قوم پرستی‘ اور’مسلم بنگال‘……کے جھگڑے کی حقیقت کو واضح کرنا ہے۔ چار کلیدی حیثیت کے حامل مراحل کا تجزیہ کرتے ہوئے، ہماری بحث ان باہم متصادم و محارب شناختوں کی ابتدا اور ارتقا کا جائزہ لے گی۔
پہلا مرحلہ جس کا جائزہ لیا گیا ہے وہ برطانوی سامراجی دور سےقبل کا زمانہ ہے کہ جس وقت بنگال مسلمان حکمرانوں کے زیرِ انتظام تھا، اور جب تصورِ ریاست کو ڈھالنے اور شکل دینے والے عوامل اس علاقے کی وسیع و زرخیز تاریخ اور تہذیبی ورثہ تھے۔
دوسرا مرحلہ برطانوی نوآبادیاتی دور کا ہے، جس میں بیرونی تسلط کے باعث کلکتہ (مغربی بنگال) سے تعلق رکھنے والی ہندوُ اشرافیہ کی کوششوں کے نتیجے میں ایک ’ہندوُ بنگالی‘ شناخت پیدا ہوئی اور پروان چڑھی۔ یہ تحریک بنگالی نشاۃ ثانیہ کے نام سے معروف ہے۔ اس نشاۃ ثانیہ کے محرکین اور حامی اپنی فکر اور نظریات ہندوُ روایات ، داستانوں اور تہذیب سے حاصل کرتے۔ نیز وہ مغربی تصورات اور فلسفوں سے بھی متاثر تھے۔
تیسرا مرحلہ بعد از برطانوی سامراجی دور پر مشتمل ہے، بالخصوص ۱۹۵۰ء تا ۱۹۷۰ء کے دوران، جب ایک بنگالی قوم پرست تحریک کا آغاز ہوا جو بالآخر پاکستان میں سِوِل جنگ اوربنگلہ دیش کی تخلیق و پیدائش پر منتج ہوئی۔ اس نو تخلیق شدہ ریاست نے بہت جلد ایک ایسا دستور و آئین اپنا لیا جو کٹر سیکولر بنیادوں پر تشکیل دیا گیا تھا۔
چوتھے مرحلے میں ہم ۲۰۱۳ء کی شاہ باغ اور شپلہ تحریکوں پر نظر ڈالیں گے، جب بنگالی بمقابلہ مسلم کی شناخت کا ٹکراؤ ایک بار پھر سامنے آ گیا۔ اس آخری مرحلے میں ہماری گفتگو کا مرکز و محور آج کامنظر نامہ ہو گا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنگالی قوم پرستی اور اسلام کے مابین تعلق ہنوز انتہائی مخالفانہ ہے۔ جس میں بعض لوگ (جیسے حکمران عوامی لیگ، بائیں بازو کے حامی اورگلوبَلسٹ ……یعنی عالمی سیاسی نظریے کے حامل……چاہے وہ عوامی لیگ کی حکومت کے حامی ہوں یامخالف ) ایک سیکولرقومی شناخت کے حامی ہیں اور بعض (یعنی دین پرست مسلمان) ایک اسلامی شناخت کی ترویج چاہتے ہیں۔
ان چار مراحل کا بغور جائزہ لیتے ہوئے، ہماری گفتگو کا ہدف و مقصد مسلمانانِ بنگلہ دیش کی شناخت کے پیچیدہ اور متعدد رخ رکھنے والے مسئلے اور اسلام سے اس کے تعلق کی دقیق و ہمہ پہلو وضاحت کرناہے ۔
باہم نبرد آزما شناختیں
بنگلہ دیش میں ’بنگالی‘ اور ’مسلمان‘ ، یہ دونوں شناختیں اکثر ایک دوسرے کے مقابل و متضاد اور ایک دوسرے سے بر سرِ پیکار سمجھی جاتی ہیں۔ بنگالی شناخت سے مراد علاقۂ بنگال (بنگلہ دیش اور بھارت کی ریاست مغربی بنگال) میں بسنے والی قوموں کی تہذیبی، لسانی اور نسلی پہچان ہے۔آج یہ ’بنگالی‘ شناخت علاقے کے بہت سے مشرکانہ عقائد و تصورات اور رسوم و رواج اورمغرب کے ’زمانۂ روشن خیالی‘(Age of Enlightenment) کے پیدا کردہ فلسفیانہ تصورات سے بری طرح متاثر ہے۔
دوسری جانب ’مسلم بنگالی‘ شناخت سے مراد بنگال کےعلاقے میں آباد مسلمانوں کی دینی اور ثقافتی شناخت ہے۔ یہ شناخت اس علاقے کی طویل و منفرد اسلامی تاریخ اور وحدتِ امتِ مسلمہ جیسے تصورات کی پیداوار ہے، جو کہ ایک ایسا تصور ہے جو تمام عالَم کے مسلمانوں کے درمیان مشترک ہے۔ ’بنگالی قوم پرستی‘ کی شناخت……جو کہ ایک سیکولر نظریہ ہے……اور ’بنگالی پن‘ جو کہ زبان اور مخصوص تہذیبی عناصر (جیسے کھانے پینے عادات، لباس اور رہن سہن، ذوق و مزہ اور مزاج و طبائع وغیرہ ) پر مشتمل ہے، کے درمیان فرق کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔
بنگلہ دیش میں ’بنگالی‘ اور’مسلم بنگالی‘ کی باہم متصادم شناختوں کے نقوش اس علاقے کی استعماری تاریخ اور ۱۹۴۷ء کی تقسیمِ ہند میں دیکھے جا سکتے ہیں، اس تقسیم کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا، جس میں علاقۂ بنگال کے مسلم اکثریتی علاقے بھی شامل تھے۔ ۱۹۵۲ء کی لسانی تحریک سے معاملات مزید خراب ہوئے جب مشرقی پاکستان کےبنگالی زبان بولنےوالےلوگوں نے اپنے اوپر زبردستی اردو بحیثیت قومی زبان مسلّط کیے جانے کے خلاف احتجاج کیا۔ اور پھر ۱۹۶۰ء کی دہائی کی بنگالی قوم پرست تحریک جو بالآخر بنگلہ دیش کی تخلیق پر منتج ہوئی۔
بنگلہ دیش میں آج بھی ’بنگالی‘ اور ’مسلم بنگالی‘ کی شناختیں بحث و تکرار اور کشیدگی و تناؤ کا سبب و محرک ہیں۔ملک پر ۵۰ سال سے قابض و حاکم سیکولر طبقے کی خواہش ہے کہ اسلامی شناخت پر سیکولر شناخت کو ترجیح دی جائے۔یہ نہ صرف حکمران عوامی لیگ کی خواہش و تمنا ہے بلکہ ان کی مخالف پارٹی بی این پی بھی یہی چاہتی ہے۔
چارتاریخی مراحل
پہلا مرحلہ: مسلم بنگال (۱۲۰۴ء تا ۱۷۵۷ء)
مشرقی بنگال میں اسلام کی تاریخ طویل اور شاندار ہے۔ آج مشرقی بنگال کی کل آبادی میں سے نوّے فیصد اہلِ اسلام پر مشتمل ہے، جبکہ مغربی بنگال (جو کہ بھارت کا حصّہ ہے)کی صرف تیس فیصد آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ مشرقی بنگال کی اصل آبادی کا اتنی بڑی تعداد میں اسلام کی طرف مائل ہونا ایک بے حد غیر معمولی امر ہے۔ بنگال کا وہ علاقہ جو مغربی بنگال کی نسبت زیادہ دور افتادہ اور دریا کے منہ کے قریب (یعنی بنگالی ڈیلٹا کے اس حصّے میں واقع جو سمندری طوفانوں اور دیگر قدرتی مصائب کا زیادہ شکار رہتا ہے ) واقع تھا، اس علاقے کی آبادی نے ڈیلٹا کے مغربی حصّے کی نسبت بہت زیادہ تعداد میں اسلام قبول کیا۔ درحقیقت اسلام کی شاندار اور قابلِ دید افزائش مشرقی بنگال ہی میں ہوئی، جو آج بنگلہ دیش کے نام سے موسوم ہے۔ مؤرخ رچرڈ ایٹن لکھتا ہے:
’’مسلمان حکمران برصغیر کے اکثر حصّے پر حاکم تھے۔ مگر ہندوستان کے اندرونی صوبوں میں صرف بنگال میں……ایک ایسا علاقہ جس کا رقبہ تقریباًانگلینڈ اور سکاٹ لینڈ کے مجموعی رقبے کے برابرہے…… غیر معمولی طور پر اصل بنگالی آبادی کی اکثریت نے حکمران طبقے کا دین اپنا لیا۔‘‘
(The Rise of Islam and the Bengal Frontier, R. M. Eaton)
اسلام نے ایک سیاسی قوت کی حیثیت سے پہلے پہل ۱۲۰۳ء میں اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی کے فاتح لشکر کےساتھ گواڑ، پندرا اور لکھناوَتی کی زمین پر قدم رکھا، (جسے بعد ازاں مسلمان حکمرانوں نے بنگلہ اور برطانوی سامراج نے بنگال کا نام دیا)۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ عرب، فارس، افغانستان اور اناطولیہ کی اقوام کا مشرقی ہندوستان کے لوگوں سے اس سے قبل کوئی واسطہ نہ پڑا تھا۔ کھدائیوں کے دوران راج شاہی کے علاقے پہاڑپور اور کَمیلا کے علاقے مینامَتی سے عباسی خلفاء کےجاری کردہ سکّے دریافت ہوئے ہیں۔ پہاڑپور میں دریافت ہونے والے سکّے پر ۷۸۸ء کی تاریخ درج ہے گویا کہ وہ ہارون الرشید کے زمانے کا ہے۔ جبکہ مینامَتی سے ملنے والا سکّہ عبّاسی خلیفہ منتصر باللہ کے دورِ خلافت کا ہے۔یہاں یہ امر بھی قابلِ توجہ ہے کہ محمد بن قاسمؒ نے ۷۱۴ء میں سندھ فتح کیا، یعنی اختیار خلجی کے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آمد سے تقریباً چار صدیاں قبل۔
اختیارخلجی کی پیشقدمی پر بنگال میں قائم ہندوُ سینا سلطنت کا آخری فرمانروا لکسمَنا سینا، اپنا تخت و تاج چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے ڈھاکہ کے قریب نسبتاً دور افتادہ اور ساحلی علاقے وِکرم پور کو اپنا مرکز بنایا۔ اس کے مرنے کے بعد سینا کے سلسلۂ شاہی کے دیگر سلاطین بھی بنگال کے اس نسبتاً کافی چھوٹے حصّے پر مزید نیم صدی تک حکومت کرتے رہے، تاآنکہ مسلمان جرنیل مغیث الدین طغرل نے مشرقی بنگال بھی فتح کر لیا۔ اس فتح کے بعد علاقے میں اسلام کے بتدریج پھیلاؤ اور مسلمانوں کی سیاسی قوت کو ہندوستان کے ان علاقوں میں جو بنگال کے قرب و جوار میں واقع تھے، بڑھنے اور پھیلنے کا موقع ملا۔
تاہم، وہ مسلمان حکمران جو بالآخر بنگال ڈیلٹا کے تمام علاقوں کو ایک انتظامی اکائی تلے متحد کرنے میں کامیاب ہوا وہ سلطان شمس الدین الیاس شاہ تھا۔۱۳۵۲ء میں الیاس شاہ نے سونارگاؤں پر قبضہ کر لیا اور یوں مشرقی ہندوستان میں ایک نئی اور متحد سیاسی قوت وجود میں آئی۔ الیاس شاہ پہلا حکمران تھا جس نے ’سلطانِ بنگلہ‘ کا لقب اختیار کیا۔ یہاں سے اس ریاست کی بِنا پڑی جو اکبر کے ’صوبۂ بنگلہ‘ اور برطانیہ کے ’بنگال‘ کے نام سے مشہور ہوا۔ الیاس شاہ نے مشرقی بنگال کے اس وقت کے دارالحکومت پر لشکر کشی کرنے سے پہلے سونارگاؤں کے حاکم فخر الدین مبارک شاہ کے دنیا سے گزر جانے کا انتظار کیا۔ مبارک شاہ کے انتقال کے بعد اس نے اپنے لشکر کے ساتھ سونار گاؤں پر چڑھائی کر دی، دارالحکومت کی فتح کے ساتھ مشرقی بنگال کی فتح مکمل ہوئی۔
مشہور مراکشی سیّاح، ابنِ بطوطہ فخر الدین مبارک کے عہدِ حکومت میں بنگلہ دیش آئے۔ وہ فخر الدین کی فرماں روائی میں علاقے کی اقتصادی ترقی و خوشحالی دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے بالخصوص یہ بات محسوس کی کہ بنگال کی برآمدات میں اہم ترین اور مرکزی مقام ٹیکسٹائلز (یعنی کپڑے سے بنی ہوئی ؍ یا بُنی ہوئی اشیاء) پر مشتمل ہے۔ ابنِ بطوطہ کے مطابق، اشیائے ضروریہ کی قیمتیں کم تھیں اور لوگ بالعموم خوشحال تھے۔اس قیام کے دوران ان کی ملاقات مشہور شیخ شاہ جلال سے بھی ہوئی۔
الیاس شاہ کے ہاتھوں سلطنتِ بنگال کے قیام اور تقریباً دو صدیوں پر محیط آزاد و خود مختار حکومت کے عرصے میں مسلمان حکمرانوں نے بہت سے دیگر ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔بنگال میں آزاد اسلامی حکومت ساڑھے پانچ سو سال کے طویل عرصے تک قائم رہی، یہاں تک کہ ۱۷۵۷ء میں نواب سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں شکست کھائی۔اس تمام عرصے کے دوران، بنگال الیاس شاہ کے قائم کیےایک انتظامی یونٹ تلے متحد رہا۔
بنگالی زبان کی نشو نما اور ترقی بھی بڑی حد تک بنگال میں اسلامی سلطنت کے قیام کی مرہونِ منت ہے۔ بنگال میں اسلامی حکومت سے قبل برہمن نظام میں ادب و سخن کے میدان میں کسی مقامی یا دیسی زبان کے استعمال کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ سینا سلسلۂ شاہی سے تعلق رکھنے والے حکمران نہ صرف سنسکرت کی سرپرستی کرتے تھے، بلکہ ان کی جانب سے تعلیمی اور ادبی مقاصد کے لیے بنگالی جیسی دیگر دیسی زبانوں کے استعمال پر سخت پابندی بھی عائد تھی۔ سینا حکمران اور طاقتور برہمن پنڈت کسی بھی دیسی زبان کو ادبی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی ہر کوشش کو یہ کہہ کر بے رحمی سے کچل دیتے تھےکہ ہندوُ مذہبی کتب اور پُرانوں (پرانی داستانوں پر مبنی مذہبی کتابیں) کو بنگالی زبان میں لکھنا یا پڑھنا انتہائی گھٹیا، نیچ اور توہین آمیز حرکت ہے۔ سنسکرت زبان کے ایک معروف شعر میں بھی یہ تنبیہ موجود ہے کہ ہر وہ شخص جو بنگالی زبان میں رامائن یا مہا بھارت سنے گا وہ راراوَہ کی بھڑکتی ہوئی جہنم میں پھینکا جائے گا۔مسلمانوں کی فتح نے مقامی لوگوں کو برہمنوں کی علم پر اس اجارہ داری سے آزاد کیا۔ بنگال میں سیاسی اسلام کی آمد اورمسلمان سلاطین کی جانب سے فیاضانہ سرپرستی کے نتیجے میں زنجیریں ٹوٹ گئیں ،حتی کہ بنگالی نژاد ہندوؤں نے بھی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ بنگالی زبان میں ادبی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ بنگالی زبان میں پہلی قابلِ ذکر تصنیف جلال الدین محمد شاہ کے زمانے میں شاعر کرِتی و اس کا کیا ہوا رامائن کا ترجمہ تھا۔ ہندوُ ماہرِ تعلیم اور بنگالی لوک رِیت کے ریسرچَر ، کلکتہ یونیورسٹی کے فیکَلٹی ممبر دِنیش چندرسین نے ۱۸۹۶ء میں لکھا:
’’بنگالی زبان اتنے زبردست شاہی ٹھاٹ باٹھ والے دربار میں کیونکر داخل ہو گئی؟ برہمن اس زبان کو کس درجہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہ تذکرہ ہو چکا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں وہ یکایک اس زبان کے حق میں اس قدر رحمدل کیسے ہو گئے؟ہمارا خیال یہ ہے کہ بنگالی زبان کی خوش بختی کا اصل سبب بنگال کی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہے۔‘‘[بنگا بھاشا و ساہتیا(بنگالی ادب کی تاریخ) از سین ایس]
بدقسمتی سے بنگلہ دیش اور مغربی بنگال، دونوں میں مسلمان بنگالی سلاطین کے بنگلہ زبان کی ترویج کے لیے ادا کیے گئے کردار کو شاذ ہی وہ پذیرائی ملتی ہے جس کا وہ مستحق ہے۔اس بے حسی اور حق ناشناسی کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں برطانوی تعلیمی نظام وِرثے میں ملا ہے، اور برطانوی استعمار کے ایک سو نوّے (۱۹۰)سالوں کے دوران ، ان مسلمان حکمرانوں سے نفرت کے سبب جنہیں برطانوی افواج نے ۱۷۵۷ء میں شکست سے دوچار کیا، ہندوستان کے اسلامی دور کی تاریخ کو مسخ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔پھر یہ بھی ہے کہ سامراجی حکمران مسلمان اقلیت کی قیمت پر ہندو اکثریت آبادی کو خوش اور مطمئن کرنا چاہتے تھے۔ طاقتور ہندو جرنیلوں اور تاجروں کے ایک گروہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک سازش تیار کی۔ ان ہندوؤں اور ان کے بعد آنے والے ان کے وارثین نے بنگال کے شاندار اسلامی دور کی تاریخ مسخ کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔
۱۹۴۷ء میں آزادی کے بعد، پاکستانی حکمرانوں نے بھی مشرقی پاکستان کے لوگوں اور ان کی تہذیب و ثقافت کو اسی طرح نظر انداز کیا۔ انہوں نے بنگال کی شاندار تاریخ اور زرخیز اسلامی وِرثے کو سمجھنا تو کجا، دریافت کرنے کی بھی کبھی کوشش نہ کی۔ ۱۹۷۱ء سے لے کر آج تک، ہم بنگلہ دیشی مستقل اس جدو جہد میں مصروف ہیں کہ مقامی طاقتوں اور اپنے بھاری بھرکم ہمسائے بھارت کی جانب سے شدید ثقافتی جارحیت کا سامنا کرتے ہوئے بھی کسی طرح اپنی اصل جڑوں اور اپنے تاریخی وِرثے کا کھوج لگائیں۔
دوسرا مرحلہ: بنگالی نشاۃ ثانیہ (۱۷۶۷ء تا ۱۹۴۷ء)
بنگالی نشاۃ ثانیہ، جو کہ بنگالی تحریک احیائے نو کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، انیسویں صدی عیسوی اور بیسویں صدی کے اوائل میں ہندوستان کے علاقۂ بنگال میں ہونے والی اس ثقافتی، معاشرتی اور فکری و نظری تبدیلی کے دور کا نام ہے جو راجہ رام موہن رائے (۱۷۷۵ء تا ۱۸۳۳ء)سے شروع ہوا اور رابندرناتھ ٹیگور(۱۸۶۱ء تا ۱۹۴۱ء) پر ختم ہوا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی بہت سے مردِ میدان ایسے آئے جنہوں نےمخصوص پہلوؤں کا احاطہ کیا۔
بنگالی نشاۃ ثانیہ کے اہم ترین محرّکین میں سے ایک علاقے میں مغربی تعلیم اور تصورات کا عام ہونا تھا۔بنگال میں مغربی طرز کے سکولوں اور کالجوں کے کھلنے سے بہت سے بنگالیوں کا مغربی ادب، سائنس اور فلسفے سے سابقہ پڑا، جس نے انہیں اپنی ذات پات پر مبنی نسل پرستی اور بت پرستی کے بے جوڑ ہندوانہ عقیدے کا از سرِ نو جائزہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اس نشاۃِ ثانیہ کی ایک نمایاں خصوصیت بنگالی زبان و ادب کی جانب رغبت اور دلچسپی بھی تھی۔ بہت سے لکھاریوں اور دانشوروں نے نہ صرف اپنے خیالات کے اظہار کے لیے بنگالی زبان کا استعمال شروع کر دیا، بلکہ اس زبان کی تعمیر و ترقی اور نشو نما کے لیے کوشش بھی کی۔
تاہم بنگالی نشاۃ ثانیہ کی حقیقت درست طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بنگالی ہندوُ کی نفسیات (سائیکی) سمجھی جائے اور یہ ادراک حاصل ہو کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔
بہت سے بنگا لی ہندوُ پلاسی کے میدان میں انگریزوں کے ہاتھوں نواب سراج الدولہ کی شکست پر بے حد خوش ہوئے۔درحقیقت نواب کی شکست ان کی دیرینہ آرزو کی تکمیل تھی، جس کے لیے وہ انگریزوں کی بہت سے مختلف طریقوں سے مدد و حمایت بھی کرتے چلے آئے تھے۔ بالخصوص وہ ہندوجنہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت اپنے اقتصادی و مالی مفادات کے حق میں بھی سود مند محسوس ہوتی تھی۔یہاں ہم خاص طور پر دو اشخاص اور ان کے خاندانوں کا ذکر بطور مثال پیش کر سکتے ہیں۔ان میں سے ایک کرشنانگر کا راجہ کرشن چندر تھا، اور دوسرا شخص کلکتہ کا ناباکرشن تھا۔
درگا پوجا کا تہوار بنگالی ہندو تہذیب کے اہم ترین تہواروں میں سے ایک ہےجو ہندو تقویم کے مطابق ستمبر-اکتوبر کے مہینوں میں منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار دس دنوں پر محیط جشن ہے۔ آج درگا پوجا کو بنگالی تہذیب کا ایک اٹوٹ انگ سمجھا جاتا ہےجسے بنگلہ دیش اور مغربی بنگال، دونوں کے ہندو بھرپور جوش و جذبے اور عقیدت کے جذبات کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس تہوار کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حق کی باطل پر فتح کی علامت اور اس کا جشن ہے۔
مگر حقیقت یہ ہے کہ اس تہوار کا ہندوؤں کی مسلم دشمنی سے گہرا اور اساسی تعلق ہے۔ بہت سے ہندو انگریزوں اور سراج الدولہ کے مابین ہونے والی جنگ کا تذکرہ ’دیوسور سنگرم‘ (یعنی دیوتاؤں اور شیطانوں کی لڑائی) کے الفاظ سے کرتے ہیں۔ایک ہندو دانشور اپنے مضمون ’’کلکتہ کا درگا تہوار‘‘ میں لکھتا ہے کہ درگا پوجا دراصل پلاسی کی فتح کی خوشی کا جشن ہے۔ اور یہ بات معروف ہے کہ پہلی بار درگا پوجا کا تہوار۱۷۵۷ء میں نادیہ اور کلکتہ میں فتح کے جشن کے طور پر ہی منایا گیا۔کرشن چندر نے نادیہ میں اس پوجا کا آغاز کیا اور نابا کرشن نے کلکتہ میں۔کلکتہ میں نابا کرشن کے گھر میں منعقد ہونے والے درگا پوجا کے جشن میں لارڈ کلائیو نے بھی شرکت کی۔ نوابِ مرشدآباد کے خزانے کی لوٹ مار اور کلائیو کی فیاضی و عنایات سے سب سے زیادہ مستفید بھی یہی دو خاندان ہوئےتھے۔
لہذا آج درگا پوجا کا جو تہوار منایا جاتا ہے وہ دراصل ایک ہندو تہوار تھا جو ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے رابرٹ کلائیو نے متعارف کروایا۔۲۸ ستمبر، ۱۹۹۰ء کو کلکتہ کے مشہور اخبار ’دی سٹیٹس مین‘ میں چھَپنے والے اپنے مضمون بعنوان ’’ جب درگا ایک ملیچھ پر سوار ہوا (When Durga rode a Mlechcha)‘‘ میں تپاتی باسو نے لکھا کہ :
’’پلاسی کی جنگ جیتی جا چکی تھی۔ سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ مگر ہندوؤں کو شیشے میں اتارنا اب بھی باقی تھا۔سراج کی شکست کو مسلمانوں پر ہندوؤں کی فتح کے طور پر پیش کرنا کافی نہیں تھا۔ رابرٹ کلائیو نے اپنے مکار و دغاباز ساتھیوں، راجہ کرشن چندر رائے اورنابا کرشن دیو کی مدد اور مشورے پر درگا پوجا کا ہندو تہوار منعقد کر کے فتح کا جشن منانے کا فیصلہ کیا۔لیکن ایک مسئلہ تھا۔ کلائیونے سال کے غلط وقت پر یہ جنگ جیتی تھی، یعنی ۲۳ جون ۱۷۵۷ء کو۔لہذا پنڈتوں سے مشورہ کیا گیا۔اور نابا کرشن دیو ایک پر تکلف ’اکل بدھون‘ ……(یعنی بے وقت بیداری) جو آج بھی کلکتہ میں منایا جاتا ہے…… منعقد کرنے پر تیار ہو گیا۔ کلائیو نے ہندوؤں کا پتہ بڑی مہارت سے کھیلا تھا، پوجا کے اس تہوار کو کامیاب بنانے میں اس کا ذاتی مفاد پنہاں تھا……اور کامیاب یہ بے حد رہا۔‘‘
پلاسی کی جنگ سے قبل درگا پوجا کا تہوار خزاں کے موسم میں نہیں منایا جاتا تھا۔مگر پلاسی کی جنگ کے بعد ، اس فتح کو ہندوؤں کی فتح کا رنگ دینے کی خاطر اور ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے کلائیو نے ایک جشن منانے کا سوچا۔یہ جشن درگا پوجا کے تہوار کے طور پر منایا گیا۔رفتہ رفتہ مسلمانوں پر فتح کا یہ جشن پوری دنیا میں ’درگا پوجا‘ کے نام سے عام ہو گیا۔
کلکتہ کے ہندو متبّر جو اپنے گھروں میں انگریزوں کی دعوتیں کیا کرتے تھے، بخوبی جانتے تھے کہ ’صاحب لوگ‘ محض مٹی کی بنی ہوئی گڑیاؤں کو دیکھ کر خوش نہ ہوں گے۔ لہذا ان ’صاحبوں‘ کے لیے گوشت پوست اور خون سے بنی گڑیاؤں کا انتظام کیا گیا۔ برطانوی افسران کی تفریحِ طبع کے لیے ناچ گانے کا اہتمام کرنے اور طوائفوں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ کچھ لکھنؤ سے لائی گئیں، کچھ برما سے اور کچھ خود انگلستان سے۔یہ عورتیں ’بائی‘ یا ’بائی جی‘ کہلاتی تھیں۔ لہٰذا ایک ہی وقت میں صحن کے ایک سرے پر ہندوؤں نے اپنے بتوں کے لیے چبوترے تعمیر کیے تو دوسرے سرے پر تفریح اور دل لگی کے لیے ناچ گانے کا اہتمام کیا گیا۔ زنا، فحاشی، موسیقی اور ناچ گانا، یہ سب ہمیشہ سے درگا پوجا کے لازمی جزو رہے ہیں۔
یہ وہ ماحول اور فضا تھی جس سے بنگالی نشاۃ ثانیہ وجود میں آئی اور اسی ماحول سے ’بنگالی‘ کی ایک مخصوص شناخت پیدا کی گئی۔یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بنگالی کے اس تصور کی تخلیق ہندو مشرکانہ تہذیب اور مغربی تصورات و نظریات کی مشترکہ کاوش تھی۔ اگرچہ ہندوستان میں انگریز حکومت کا مرکز کلکتہ میں رہا، اس کے باوجود مشرقی بنگال کے لوگ جو کہ زیادہ تر مسلمان تھے، آہستہ آہستہ اور دیدہ و دانستہ اپنے حقوق سے محروم کر دیے گئے۔
بہت سے مسلمان زمینداروں سے ۱۷۹۳ء کے ’پرماننٹ سیٹلمنٹ قانون‘ کے تحت، ان کی زمینیں چھین لی گئیں۔پھر اسی قانون کی مدد سے اور انگریز کی آشیرباد سے بہت سے ہندو منشیوں کو خود زمیندار بن بیٹھنے کا وافر موقع ہاتھ لگا۔ انگریزوں نے بنگالی دہقانوں (جن کی اکثریت مسلمان تھی) کے لیےبھی محصول کا ایک نہایت سخت نظام متعارف کروایا۔انگریز حکمرانوں کی خفگی بھرے رویّے اور مسلمان اشرافیہ کو دیوار سے لگانے کے دستور کے نتیجے میں تعلیم یافتہ بنگالی ہندوؤں پر مشتمل اشرافیہ کا ایک طبقہ وجود میں آیا۔یہ مالدار اور صاحبِ ثروت لوگ تھے جو سِوِل سروس، عدلیہ اور یونیورسٹیوں میں اہم عہدوں کے حامل تھے۔
اگرچہ ہندو اور مسلمان ایک ہی معاشرے میں اور ایک ہی افسرِ شاہی کے ما تحت زندگی گزارتے تھے، اس کے باوجود ان کی تہذیبی و ثقافتی زندگیاں ایک دوسرے سے مماثل نہ تھیں۔بنگالی مسلمان علاقے کے آزاد و خود مختار مسلمان حکمرانوں کی شکست کے سبب انگریزوں اور ان کے نظامِ تعلیم کے مخالف تھے، اور بالخصوص ان کی انگریزی زبان کے بے حد خلاف تھے۔ جبکہ ان کے برعکس ہندو انگریزوں کو اپنے گورے نجات دہندہ تصور کرتے تھے۔
تعلیمی، ادبی اور اقتصادی میدانوں میں ہندوؤں کی قیادت جلد ہی ہندوؤں کی تہذیبی برتری اور غلبے کی شکل میں نظر آنا شروع ہو گئی، لیکن یہ ایک ایسا سلسلہ تھا جس سے مسلمان ناخوش تو تھے،مگر جسے روکنے یا اس کا سدّباب کرنے کے لیے کچھ نہیں کرسکتے تھے۔
برطانوی راج کے دورِ آغاز میں اسلام اور مسلمانانِ ہندوستان کی تحقیر کرنا ااور ان کا مقام و مرتبہ گھٹانا عام دستور تھا۔ہندوستان کی مغل سلطنت کے بچے کھچے ڈھانچے پر برطانوی استعماری قبضے کا جواز پیدا کرنے کے لیے انگریز لکھاریوں، اہلِ علم و دانش، بیوروکریٹس اور مشنریوں کو یہی آسان اور مناسب حل سوجھا کہ مسلمانوں کی نہایت خراب اور خستہ حال تصویر کشی کی جائے۔ جلد ہی ہندوستان کے نئے ابھرنے والے لکھاریوں نے بھی انہی برطانوی علمی و ادبی روایات کی نقل اور پیروی کی۔ ان ہندو مصنفین اور لکھاریوں نے ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں (کے کردار ) کو پیش کرنے میں ایک خاص قسم کی کج روی کا مظاہرہ کیا۔ ان کا رویّہ و سلوک یورپین اورئینٹلز(وہ یورپی افراد جو مشرقی دنیا بالخصوص جنوبی ایشیا میں دلچسپی رکھتے تھے) کی فکری روش کے بے حد قریب تھا جو ایشیا میں بڑھتے اور پھیلتے ہوئے استعمار کی حمایت کیا کرتے تھے۔ بیسویں صدی کے نصفِ اول میں بنگال میں مسلمانوں کے علیحدگی پسند خیالات کے پیچھے انہی بے شمار ہندو لکھاریوں اور اصحابِ علم و دانش کا ہاتھ تھا جو مسلمانوں کی کردار کشی کرنے میں پیش پیش رہے تھے۔
تیسرا مرحلہ: مشرقی پاکستان میں بنگالی قوم پرست تحریک (۱۹۵۲ء تا ۱۹۷۵ء)
۱۹۵۰ء اور ۶۰ء کی دہائی میں مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان کی حاکم سیاسی اور فوجی اشرافیہ کے ظلم کے خلاف عام غصّہ و ناراضگی پائی جاتی تھی۔ یہ ناراضگی حق بجانب بھی تھی کیونکہ فوجی و سیاسی اشرافیہ پر مشتمل یہ گروہ مشرقی پاکستان کا باقاعدہ و منظّم استحصال بھی کرتا اور وہاں کے لوگوں کی تذلیل و توہین بھی۔ حالانکہ جن لوگوں کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا رہا تھا ان میں اکثریت ان مسلمانوں پر مشتمل تھی جنہوں نے برضا و رغبت پاکستان بنانے کی حمایت کی تھی۔ حد تو یہ تھی کہ مغربی پاکستان کی یہ اشرافیہ مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کے دین و ایمان پر سوال اٹھانے سے بھی نہ چُوکی۔معاشی استحصال، سیاسی و ثقافتی تفریق اور تذلیل و تحقیر پر مبنی رویّے عوام میں غصّے و نفرت اور تلخی و خفگی کے جذبات پھیلانے کا سبب بنے۔
عوام کے ان جذبات سے سیکولر سیاسی قائدین نے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک ’بنگالی قوم پرست(نیشنلسٹ) تحریک‘ شروع کی جس کے بہت سے نظریات و تصورات بنگالی نشاۃ ثانیہ سے ادھار لیے گئے تھے۔ بنگالی قومیت یا نیشنلزم کی بحث چھیڑ کر مڈل کلاس دانشوروں کے گروہوں نے سیکولر سیاست کے لیے راہ ہموار کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔جہاں ان گروہوں کی فکر کا ماخذ و منبع بنگالی نشاۃ ثانیہ تھی وہیں یہ لبرل سوشلزم اور مارکسزم کے بھی قائل و داعی تھے۔ یہ مغربی آزاد خیالی (لبرل ازم) اور مارکسزم سے اپنے سیکولر خیالات کے لیے فلسفیانہ دلائل حاصل کرتے، اور رابندرناتھ ٹیگور(جس نے ۱۹۱۳ء میں ادب میں نوبل انعام حاصل کیا ) کی نظموں ، ترانوں ، ڈراموں اور مضامین کو سیکولر سوسائٹی اور سیکولر سیاست کے لیے بطور علامت استعمال کرتے۔ اپنے ان خیالات کو تقویت بخشنے کے لیے وہ دلائل وہاں سے ڈھونڈ کر لاتے جو بقول ان کے بنگالی تہذیب کا استعماری غلامی سے غیر متاثر شدہ حصّہ تھا۔ ان گروہوں کی یہ سرگرمیاں نئی نہیں تھیں، بلکہ یہ ۱۹۳۰ء کی دہائی کے اواخرسے فعال تھے۔
۱۹۶۰ء کی دہائی میں ، ملک کی سیاسی اعتبار سے گرما گرم فضا میں دانشوروں اور طلبہ لیڈروں کے ایک دوسرے گروہ نے ایک سیکولر جمہوری ریاست کا مطالبہ اور اس کی حمایت شروع کر دی۔ یہ بنگالی دانشور جدیدیت (ماڈرنزم)، لبرل سوشلزم اور مارکسزم کے نظریات سے متاثر تھے۔ کمیونزم اور لبرلزم کے ملاپ نے انہیں ایک ایسی آزاد و خود مختار بنگلہ دیشی ریاست قائم کرنے کا داعیہ و محرک دیا کہ جس کے ۷۲ء کے آئین میں ان کی حمایت سے جمہوریت، لادینیت (سیکولرزم)، سوشلزم اور قوم پرستی (نیشنلزم) بنیادی ریاستی اصول و مبادی ٹھہرے۔
یہ امر بھی ظاہر ہے کہ دانشوروں کے اس گروہ نے مشرقی پاکستان پر مغربی پاکستان کے ظلم کے پس منظر میں مارکسسٹ انقلاب کی حمایت کی۔ وہ لینن کی ’’روس کی اقتصادی تاریخ‘‘(Economic History of Russia)کی تعریف و تحسین کرتے، بعض نے بنگالی زبان میں لیون ٹروٹسکی کی ’’مستقل انقلاب کا تصور‘‘(Idea of Permanent Revolution ) کا ترجمہ بھی کیا۔ مڈل کلاس بنگالی دانشوروں کے اندرونی حلقے کے اندازِ فکر کوسمجھنے کی خاطر یہ بحث و تحقیق خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ کیونکہ یہی وہ طبقے تھے جس سے تعلق رکھنے والے افراد آزادی کے بعد بنگلہ دیش میں سیکولر بحث کو چھیڑنے ، ڈھالنے اور رخ دینے کے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوئے۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ اس طبقے کے افراد کا آزادی کے بعد بنگلہ دیش کا آئین لکھنے اور تیار کرنے کے عمل سے گہرا اور اساسی تعلق رہا۔وہی آئین و دستورِ بنگلہ دیش جو سیکولرزم، بنگالی قوم پرستی، جمہوریت اورسوشلزم کو ریاست کے بنیادی اصول کا مقام دیتا تھا۔
یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ مشرقی بنگال کے لوگوں کی اکثریت مارکسزم، سیکولرزم اور انقلاب کی حامی نہیں تھی۔ان کے دلوں میں پاکستان کی اسلامی شناخت کے خلاف کوئی بغض و نفرت نہیں تھی۔ مشرقی بنگال کی آبادی کی اکثریت مسلمان تھی، وہ اپنے آپ کو مسلمان تصور بھی کرتے تھے، مگر ساتھ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ بنگالی زبان کو تسلیم کیا جائے اور مغربی پاکستان کے باشندوں کی مانند انہیں بھی مساوی عزت و احترام اور حقوق دیے جائیں۔ یہ بات قابلِ فہم ہے کہ وہ حکمران طبقے کے خلاف غم و غصّے کے جذبات رکھتے تھے۔ مگر ان کے اس غصّے اور مجروح جذبات کو سیکولر سیاسی لیڈروں اور بائیں بازو کے حامیوں نے نہایت مہارت سے اپنا الّو سیدھا کرنے کے لیے استعمال کیا۔عوامی لیگ کی حکومت، طلبہ تنظیمیں اور ان کے دانشور ساتھی پاکستانی فوج سے اظہارِ برأت کرنے اور ملک کی بھاری اکثریت کے مسلم تہذیبی وِرثہ و روایات کے ساتھ گہرے جذباتی تعلق اور لگاؤ کی توہین کرنے میں کوئی تمیز یا فرق روا نہ رکھتے۔
بنگلہ دیش کے وجود میں آنے کے بعد ایک سیکولر آئین کا مسوّدہ تیار کیا گیا۔ستم ظریفی تو یہ ہے کہ بنگالی قومیت یا قوم پرستی کے نام پر عوامی لیگ کی حکومت نےاس مسلم تاریخ، تہذیب اور سیاست کی تمام علامتیں مٹانے کی کوشش کی کہ جس کے باعث ۷۱ء میں بنگلہ دیش کا قیام ممکن ہو پایا تھا۔ قوم پرستی (نیشنلزم)، لادینیت (سیکولرزم)، جمہوریت اور سوشلزم……کہ جس کے مجموعے کو (مجیب کی نسبت سے) ’مجیب ازم‘ کہا جانے لگا، ملک کی نئی نظریاتی کھچڑی تھی اور ’جے بنگلہ‘ کا نعرہ بنگلہ دیش کا تازہ محبِ وطن نعرہ تھا۔ حکومت عوام کے سیاسی جذبات سے مکمل صرفِ نظر کرتے ہوئے ایک بے حد واضح انتقامی جذبے کے ساتھ سڑکوں اور تعلیمی اداروں کے نام بدلنے جیسے لایعنی کاموں میں مشغول تھی ۔
عوامی لیگ کی حکومت، طلبہ تنظیمیں اور ان کے دانشور ساتھی پاکستانی فوج سے اظہارِ برأت کرنے اور ملک کی بھاری اکثریت کی مسلم تہذیبی وِرثہ و روایات کے ساتھ گہرے جذباتی تعلق اور لگاؤ کی توہین کرنے میں کوئی تمیز یا فرق روا نہ رکھتے۔عوامی فنکشنز کا آغاز تلاوتِ قرآن کریم سے کرنا پرانی روایت تھی۔ مگر بنگلہ دیش کی نئی حکومت نے ۷۲ء میں اس روایت کو بھی ختم کر دیا۔پاکستانی دور میں ہفتہ وار تعطیل کا دن جمعۃ المبارک ہوا کرتا تھا، لیکن بعد ازاں اسے بھی تبدیل کر کے چھٹی کا دن اتوار مقرر کر دیا گیا۔ ایک اور انتہائی قدم اسلامی موقف کی حامل تمام سیاسی تنظیموں اور گروہوں پر پابندی لگانا تھا۔
۷۵ء میں جب فوج نے مجیب کا دھڑن تختہ کیا تو مجیب اپنے خاندان سمیت قتل کر دیا گیا۔ مگر اس کے بعد آنے والی حکومتیں بھی اپنے سیکولر منہج پر قائم رہیں۔ وہ انسانی ساختہ قوانین کے بل پر حکومت کرتی رہیں اور قانونِ الٰہی کو بزور دَباتی رہیں۔ ہاں مجیب دور کی کھلی اور واضح سیکولر پوزیشن سے ہٹ گئیں اور انہوں نے……بہت حد تک پاکستان کے حالیہ و سابقہ حکمرانوں کی طرح……اسلامی شناخت کے بعض ظاہری اور سطحی پہلؤوں کو اپنانا شروع کر دیا۔
آج بنگلہ دیش میں اسلام پر چہار جانب سے ایک یلغار ہے، مگر بنگلہ دیش کے اہلِ اسلام پھر بھی بے حد مضبوطی سے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام عالم میں پھیلی امتِ مسلمہ کی محبت کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔
۱۹۵۰ء تا ۱۹۷۰ء کے عرصےکے دوران ، مارکسزم کی جانب مائل متوسط طبقے کے دانشورمختلف مغربی سیاسی خیالات و نظریات کی روشنی میں بنگالی قوم پرستی کی تعریف و تشریح کیا کرتے تھے۔ مجیب الرحمن کے مرنے تک یہ دانشور ایک سیکولر قسم کی بنگالی قوم پرستی کے تصور کو ڈھالنے کے کام آئے۔ مگر ان کی یہ مہم اس لیے ناکام ہو گئی کیونکہ ان کا یہ بیانیہ مسلمان عوام کی حقیقت سے دور اور کٹا ہوا تھا۔
چوتھا مرحلہ: شاہ باغ بمقابلہ شَپلہ (۲۰۱۳ء تا حال)
چوتھا مرحلہ ۲۰۱۳ء میں تحریکِ شاہ باغ سے شروع ہوتا ہے۔ اس تحریک نے جماعتِ اسلامی کے دینی قائدین کو ۷۱ء کے جنگی جرائم کے الزام کی بنیاد پر ان کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا۔ بہت سے غیر جانبدار مبصرین……جن میں مغربی سیکولر مبصرین بھی شامل ہیں……نے کہا کہ یہ الزامات اور ان کے نتیجے میں ہونے والے مقدمے کے پیچھے سیاسی محرکات کار فرما تھے اور یہ تاریخی حقائق پر مبنی نہ تھے۔
تحریکِ شاہ باغ جماعتِ اسلامی کے تمام قائدین کو قتل کرنے کا مطالبہ لے کر آئی تھی۔ یہ تحریک بنگلہ دیش میں مذہبی سیاست پر مکمل پابندی عائد کرنے کے حق میں تھی جس کی خاطر اس نے باقاعدہ سیاسی مہم بھی چلائی۔بنیادی طور پر اس تحریک کی حمایت کرنے والوں میں بائیں بازو کے طلبہ گروہ، دانشور، عوامی لیگ اور بالخصوص بھارت شامل تھے۔ تحریک کی سرگرمیوں میں شمولیت اختیار کرنے والوں کے لیے مفت کھانے اور میڈیا کوریج کی ضمانت دی گئی تھی جس کے سبب بہت سے لوگ ان کے جلسوں میں شامل ہوتے۔بہر کیف، یہ تحریک بنگلہ دیش کے عوام کی نمائندگی کرتی تھی۔
قابلِ توجہ امر یہ تھا کہ تحریکِ شاہ باغ کے فعال ترین منتظمین اور بے باک ترین محرکین میں وہ بلاگر شامل تھے جو کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین (رضی اللہ عنہن) کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ الحمد للہ ، اللہ کے فضل سے مجاہدین ان شاتمینِ رسول ﷺ میں سے رجیب نامی ایک گستاخ شخص کو تحریکِ شاہ باغ کے شروع کے دنوں میں ہی قتل کرنے میں کامیاب رہے۔اس قتل پر بنگلہ دیش کی حالیہ وزیرِ اعظم حسینہ رجیب کے گھر گئی اور اس کو ’دوسری جنگِ آزادی کا پہلا شہید‘ قرار دیا۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد جب رجیب اور تحریکِ شاہ باغ کے دیگر قائدین کی بہت سی فحش (پورنوگرافک)، اور اسلام دشمنی پر مشتمل تحریریں عوام کے سامنے آئیں تو اس تحریک کے بارے میں عوامی فہم بالکل بدل گیا اور لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا۔
اسی دوران قومی مدرسے کے علماء کی قیادت میں حفاظتِ اسلام نامی تنظیم نے ایک تحریک کا آغاز کیا جس نے شاتمینِ رسول ﷺ کے لیے موت کی سزا (مقرر اور نافذ کرنے) کا مطالبہ کیا۔ایک بار پھر پورا ملک تقسیم ہو گیا۔شاہ باغ تحریک تو ایک طرف ہو گئی، اور عوامی توجہ حفاظتِ اسلام تحریک کی جانب مبذول ہو گئی اور یہ تحریک زور پکڑنے لگی۔ تاہم ۵ مئی ۲۰۱۳ء کوحفاظتِ اسلام تحریک نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا جس کا اختتام ڈھاکہ کے عظیم چوک شَپلہ چتر پر ہونا تھا۔ حکومت نے حفاظتِ اسلام کے مظاہرین پر فائر کھول دیا جس سے بہت سے لوگ قتل ہو ئے۔اس کے بعد شدید ترین حکومتی دباؤ کے سبب یہ تحریک دَب گئی جبکہ شاہ باغ تحریک آہستہ آہستہ خود ہی بجھ گئی۔
مگر ملک بری طرح شَپلہ اور شاہ باغ کے درمیان تقسیم ہو گیا۔عوامی لیگ کی حکومت نے عام عوامی جذبات کا رخ محسوس کرتے ہوئے آہستہ آہستہ تحریکِ شاہ باغ اور اس کے جارحانہ سیکولرزم سے دور ہٹنا شروع کر دیا۔
اگرچہ تحریکِ حفاظتِ اسلام ان گستاخ بلاگرز کو سزا دلوانے میں ناکام رہی، مگر الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے القاعدہ برِّ صغیر کے مجاہدین ان گستاخوں میں سے کئی کو سزا دینے میں کامیاب رہے۔القاعدہ کی عملیات ان گستاخوں کے منہ بند کرانے اور سیکولر بنگالی قوم پرست نظریے کی ابھرتی ہوئی لہر کو روکنے میں بے حد کامیاب رہیں۔ مگر ۲۰۱۸ء کے بعد سے بنگالی قوم پرستی ایک بار پھر دن بدن بڑھتی ہوئی شدت سے ظاہر ہو رہی ہے اور کوئی بھی اسلامی تحریک اس کے خلاف کما حقہ مزاحمت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔
آج بنگالی قوم پرستی اور مسلم بنگال کی شناخت کے مابین تنازع ملک کو تقسیم کرنے والا سب سے بڑا اور مرکزی نظریاتی تنازع ہے۔
حاصلِ کلام
اسلام تمام تہذیبوں کو اپنے اندر سمونے کی صلاحیت رکھتا ہے، بشرطیکہ ایسے عناصر جو بنیادی اسلامی تعلیمات سے ٹکراتے ہوں، انہیں حذف کر دیا جائے۔ اسلام کی اس طبیعت و مزاج سے مسلم معاشرے میں تنوع اور قبولیت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔
تمام دنیا میں بسنے والے مسلمان مختلف زبانیں بولتے ہیں، ان کے کھانے مختلف، لباس کی عادات رنگا رنگ اور تہذیبی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ مگر ان تمام اختلافات کے ساتھ بھی وہ اسلام کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں۔اسلام اپنے پیرو کاروں پر کوئی بھی مخصوص زبان یا رسم و رواج مسلّط نہیں کرتا، نہ ہی یہ کسی ایک نسل کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے۔اگرچہ عربی زبان کا ایک خاص مقام ہے چونکہ عربی زبان نہ صرف زبانِ وحی ہے بلکہ خود رسول اللہﷺ کی زبان ہے کہ جس میں انہوں نے اسلام کی تعلیمات اولین مسلمانوں تک پہنچائیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اورر دیگر علماء نے اس بابت لکھا ہے کہ اگرچہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت یا فوقیت حاصل نہیں، اور نہ کسی عجمی کو عربی پر، مگر مسلمانوں کے لیے عربوں اور عربی زبان سے محبت رکھنا فطری امر ہے، اور ایمان کا حصّہ بھی(اور اس کا سبب وہی ہے جو پہلے ہم نے بیان کیا)۔اس رویّے سےایک مسلمان معاشرے میں مختلف تہذیبی شناختیں پنپنے کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔
تاہم اس قبولیت ِعام کے لیے بھی ایک شرط ہے۔اور وہ یہ کہ اسلام اور امت ِ مسلمہ مسلمانوں کی شناخت کے اہم ترین اور نمایاں ترین پہلو ہونے چاہئیں۔ہر وہ عنصر جو ان دو پہلوؤں سے ٹکراتا ہو اسے ردّ کرنا ہو گا۔اس میں وہ معاشرتی رسم و رواج بھی شامل ہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوں جیسے تعصب اور تفریق، اور مختلف عقائد، رواج اور وہ تہوار بھی جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوں۔
اسلام برّصغیر کے رہنے والوں سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ لازماً عربوں کی غذائی عادات اپنائیں، نہ ہی شمالی افریقہ سے تعلق رکھنے والوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ افغانوں کا طرزِ لباس اختیار کریں۔نہ ہی المغرب کے مسلمانوں پر یہ زبردستی کرتا ہے کہ وہ الجزائر کے مسلمانوں کے رسم و رواج اپنائیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی مسلمانوں پر اس قسم کی کوئی زور زبردستی کرتا ہے اوراللہ نے جو وسعت عطا کی ہے اسے مسلمانوں کے لیے تنگ کرتا ہے، تو وہ محض اس امت کو کمزور کرے گا۔ کیونکہ عصبیت……کسی خاص گروہ کی شناخت……اپنی قوم، زمین اور زبان سے محبت اور وفا……یہ وہ جذبات ہیں جو تمام انسانوں کے اندرمخفی ہوتے ہیں۔ اور جب یہ جاگ جائیں تو کوئی بھی انسان مکمل طور پر ان کی کشش سے بچ نہیں پاتا۔ سو اگر ایک شخص کی زمین، قوم یا رسوم و رواج پر بلاوجہ حملہ کیا جائے تو یہ لامحالہ تلخی اور تنازع کا باعث بنے گا۔
مجموعی طور پر اسلام بنی نوع آدم میں ان کے تہذیبی پس منظروں سے قطع نظر، بھائی چارے اور اتحاد و اتفا ق کے جذبات کو فروغ دیتا ہے۔جب تک شرعی مطالبات پورے کیے جا رہے ہوں، ذاتی پسند نا پسند اور تہذیبی و ثقافتی چناؤ اور اختیار کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اسلام معاشرے میں تنوع اور قبولیت کی اجازت دیتا ہے، تآنکہ دین کے کسی بنیادی اصول پر سمجھوتہ نہ ہو رہا ہو۔یوں اسلام مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو ، ایک عقیدے کے پرچم تلے اکٹھا اور متحد کرتا ہے۔
تہذیبی و ثقافتی اختلافات اور اس قسم کے دیگر موضوعات پر بات کرتے اور رائے دیتے ہوئے ضروری ہے کہ یہ بنیادی اصول ذہن نشین رہیں، کیونکہ ان اصولوں سے ہٹنے کا نتیجہ، چاہے وہ لاپروائی کی بنا پر ہو یا شدت پسندی کی، مگر اس کا نتیجہ مسلمانوں میں پھوٹ، افتراق، مخاصمت اور حتی کہ جارحیت کے سوا کچھ نہیں۔
٭٭٭٭٭