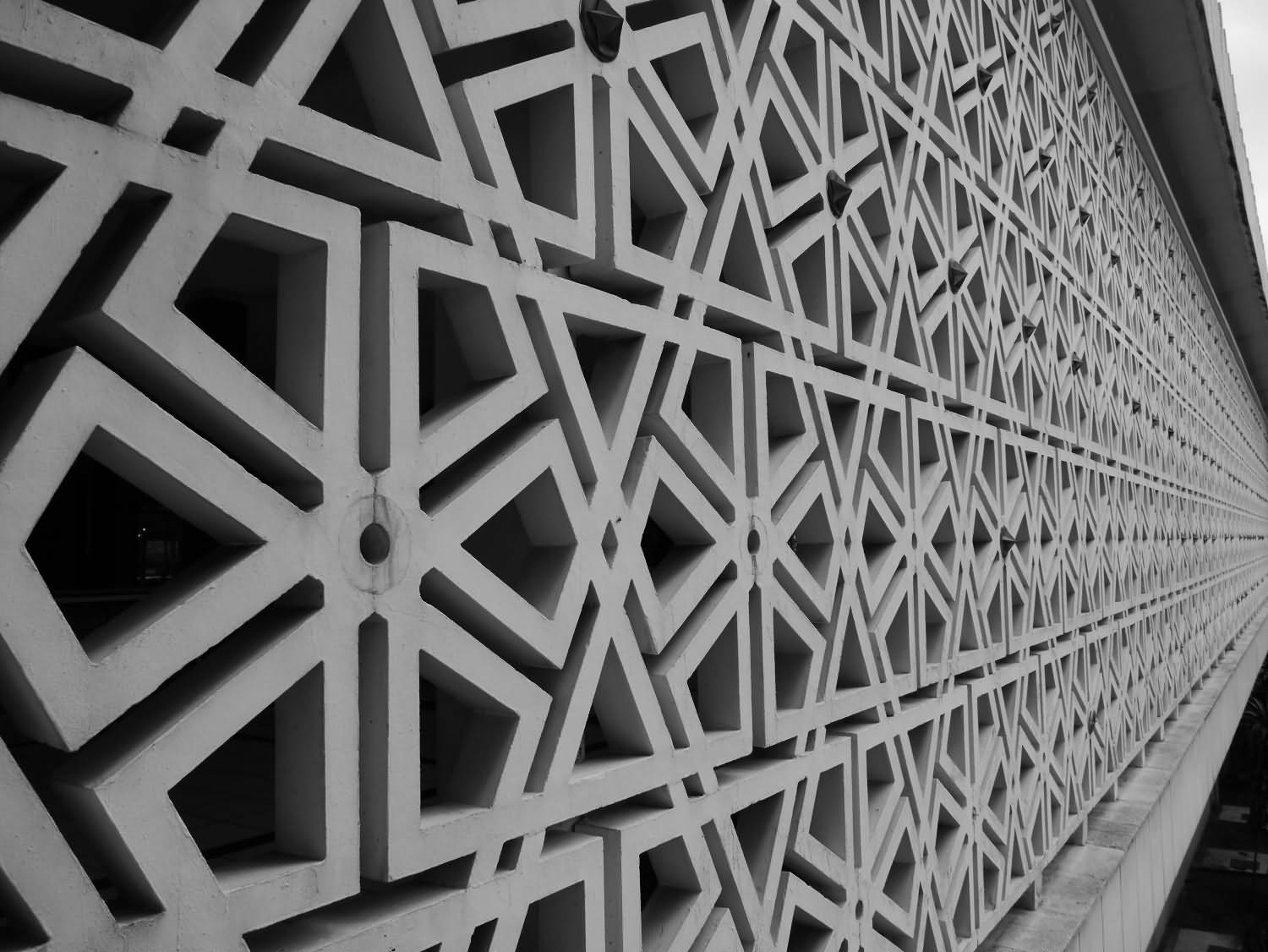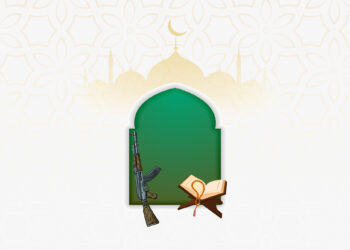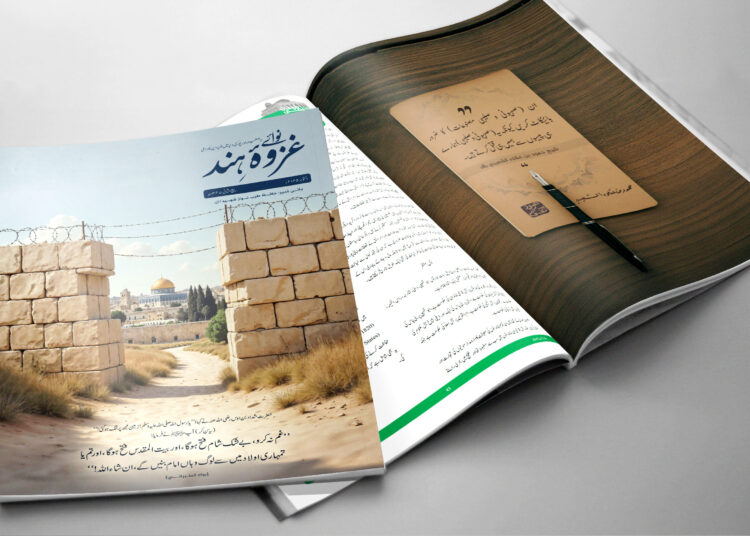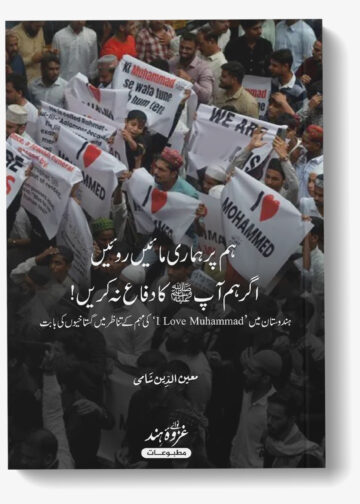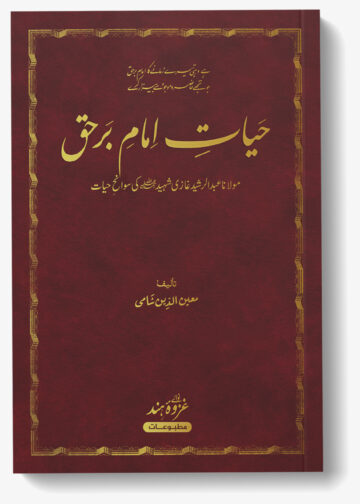لگ بھگ گزشتہ ایک صدی سے مسلم دنیا میں ایک مستقل اور بدقسمت رجحان موجود ہے ، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے اس معیارِ قبولیت کوجسے طبعاً ہمارا پیمانہ ہونا چاہیے، اس کو بنیاد بنانے کے بجائےمغرب کے عمومی مزاج کی بنیاد پر نئے نظریات و تصورات کو اپنایا جاتا ہے اور پھر ان نئے نظریات کو بنیاد بناتے ہوئے اقدامات کیے جاتے ہیں ۔ آنے والی سطور میں، میں اپنی بات کا مفہوم واضح کرتا ہوں۔
جب یورپی سامراجی نوآبادکاروں نے اسلامی دنیا میں قدم رکھا تو مغرب کی نقّالی کا ایک منحوس سلسلہ شروع ہو گیا۔مسلمان معاشرے کا کوئی نہ کوئی حصّہ مسلسل مغرب کی تقلید کرنے کی کوشش میں مصروف رہتا۔ بالعموم ان پہلوؤں کی تقلید کرنے کی کوشش کی جاتی جو ان نقّالوں کے خیال میں مغرب کو عالمِ اسلام سے بہتر و بالاتر بناتے تھے۔لہٰذا برّ صغیر میں مغرب کے وفادار و اطاعت گزار غلام ’سر‘ سید احمد خان نے وہ تحریک شروع کی جو بعد ازاں ’اسلامی جدّت پسندی ‘ کے نام سے معروف ہوئی۔ اس تحریک سے وابستہ افراد قرآن مجید میں موجود ہر شئے کی تشریح و توضیح نیچرلزم1 کی روشنی میں ، اور اس زمانے کی ’جدید سائنس‘ کی بنیاد پر کرتے تھے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے بہت سے تو حدیث کے ہی یکسر منکر ہو گئے، اور بہت سوں نے دینِ اسلام کے کئی بنیادی پہلوؤں کا انکار کر دیا۔ یقیناً قارئین سر سیّد احمد خان اور اس جیسوں کے معروفِ زمانہ تجاوزات و انحرافات سے بخوبی واقف ہوں گے۔
جب برطانوی سامراج مصر میں وارد ہوا تو محمد عبدہ کے ذریعے اسلامی جدیدیت کی ایک ملتی جلتی لہر کا آغاز ہوا۔ انگریزوں کی مدد سے محمد عبدہ الاظہر کے شیخ بھی بن گئے۔ سید احمد اور اس کے متّبعین کی طرح، (مصر کے) یہ جدّت پسند سولہویں صدی میں مارٹِن لوتھر کی مذہبِ عیسائیت میں شروع کی گئی تحریکِ اصلاح کی طرز پر اسلام میں بھی اصلاح و تجدید کرنا چاہتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح اسلام ’جدید‘ (دور سے ہم آہنگ)ہو جائے گا۔ ایوِلِن بیرنگ جو ’لارڈ کرومر‘ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اپنی کتاب بعنوان ’جدید مصر ‘ میں اس شک کا اظہار کرتا ہے کہ نجانے یہ جدّت پسند دینِ اسلام پر فی الحقیقت ایمان رکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ ایک کافر ہوتے ہوئے بھی اس نے یہ محسوس کیا کہ ان تجدید پسندوں کی اصل روح اور ان کی شناخت دومتضاد حصّوں میں بٹی ہوئی تھیں۔
بیسویں صدی کے نصفِ اوّل میں عالمِ اسلام نے دوبارہ دو ایسی تحریکوں کا مشاہدہ کیا جو مغرب کی نقّالی میں اٹھی تھیں۔ ان میں سے ایک کمیونزم سے متاثر تھی، اور دوسری قوم پرستی یا نیشنلزم سے۔ مسلم دنیا کے بہت سے اہلِ علم و دانش کمیونزم کے سحر میں مبتلا ہو گئے اور کمیونزم کو عدل و انصاف اور تہذیب کی معراج تصور کرنے لگے۔سو انہوں نے نہایت سرگرمی اور دلجمعی سے مسلمانوں کو کمیونزم اپنانے کی تحریض دلائی اور کمیونزم کو عین اسلام ثابت کرنے کے لیے تحریروں کے انبار لگا دیے۔ انہوں نے قرآن و حدیث کی تفہیم و تفسیر کمیونزم کی عینک لگا کر کی اور زکوٰۃ و صدقات سے متعلقہ آیات کو حقِ ملکیت کے خلاف آسمانی ہدایت کے طور پر پیش کیا۔
پھر قوم پرستی کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مغرب سے برآمدہ اس غلیظ نظریے کی بنیاد پر عالم ِ اسلام کے بعض افراد نے عرب قوم پرستی کی بدنامِ زمانہ تحریک شروع کی۔ دیگر لوگوں نے مقامی سطح پر قوم پرستی پر مبنی سیاسی مہمات شروع کیں اور ان کی تائید و توثیق کے لیے اسلام ہی کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ برّصغیر میں ہم نے ’مسلم قوم پرستی ‘ کے نام سے آپ اپنی ہی نفی کرنےوالی ایک تحریک وجود میں آتے دیکھی جو بنیادی طور پرمسلم اکثریت والی ایک سیکولر و لبرل ریاست کا تصوّر لے کر اٹھی تھی۔ واضح طور پر یہ اسلامی طرزِ حکومت حقیقی تصوّر کی ایک نہات مسخ شدہ، بیہودہ اور ذلت آمیز شکل تھی۔
سرد جنگ کے دوران عالمِ اسلام پر سوویت روس کے اثر و رسوخ کی بڑھتی اور پھیلتی ہوئی لہر کو روکنا امریکہ کی خواہش و ضرورت تھی، لہٰذا اس نے بعض طاغوت حکمرانوں کی ’اسلامائزیشن‘…… (جو کہ مسلمانوں کو خوش و مطمئن کرنے کے لیے محض ایک جھوٹے بہلاوے یا سبز باغ کی حیثیت رکھتی تھی) کی کوششوں کی حمایت کی اور ساتھ دیا۔ پھر جب عالمِ عرب کے ہاتھ تیل کی دولت آ گئی تو یکا یک وہ بے حد مالدار ہو گئے، مگر اس دولت کو امّت کی بھلائی اور بہتری کے لیے استعمال کرنے کے بجائے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس دولت سے نام نہاد اسلامی بینکاری کا سیکٹر تخلیق کیا جائے گا۔
مگر یہ کام بھی سیکولر و لادین حضرات کا نہیں تھا، بلکہ بہت سے مسلمان اہلِ علم، مفکر و دانشور حتی کہ بعض علماء نے بھی اس کوشش میں حصّہ ڈالا۔ آج اسلامی بینکاری ایک کھربوں ڈالر کی صنعت ہے، مگر اس کے باوجود اراکان، شام، کاشغر اور دیگر بے شمار جگہوں پر ہمارےبھائی اور بہنیں روزانہ بھوک اور فاقوں کا عذاب جھیلتے ہیں۔ اس روش سے عالمی کفری نظام تو مضبوط ہوا، لیکن ہماری امّت کواس سے کچھ نفع حاصل نہ ہوا ۔
پھر سوویت روس کے ٹوٹنے اور بکھرنے کے بعد جب مجاہدین ہبلِ عصر اور کفر کے سانپ کے سر، امریکہ کے خلاف بڑی جنگ شروع کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے، اسلامی تحریکات کا رخ جمہوریت کی جانب مڑ گیا۔اس سے پہلے بھی جمہوریت کے ساتھ معمولی نوک جھونک تو چلتی چلی آرہی تھی، مگر نوّے کی دہائی میں یہ سنجیدہ رخ اختیار کر گئی۔اور ستمبر ۲۰۰۱ء کے مبارک اور عظیم الشان حملوں کے بعد جب ایمان اور کفر ایک دوسرے کے خلاف صف آراء ہو گئے، اور بش ابن بش نے بر سرِ عام یہ کہہ کر کہ ……’’یا تم ہمارے ساتھ ہو یا دہشت گردوں کے ساتھ‘‘……اسلام کے خلاف جنگ کا آغاز کردیا، تو بہت سی اسلامی تحریکیں جمہوریت کے سامنے بچھ گئیں۔
مغرب نے مصر کی اخوان المسلمون، تیونس کی النہضۃ، الجزائر کی ایف آئی ایس(اسلامِک سالوِیشن فرنٹ) کو یہ باور کرایا کہ ’اگر تم لبرل جمہوری اقدار کے ساتھ چلتے ہو تو ہم (یعنی مغرب) تمہارے ساتھ ربط و تعلق رکھیں گے،تمہیں قبول کریں گے! مگر ا س کے لیے ضروری ہے کہ تم معتدل (moderate) مسلمان بنو۔ اور معتدل بننے کے لیے جمہوریت کو اپنائے رکھنا ناگزیر ہے۔پھر ہی تمہارا معاشرہ ترقی کرے گا! اور تم آزاد ہو گے! اور اگر تم اپنی بے لچک دعوت پر ہی اصرار کرتے رہے اور جہاد کے رستے کو اپنایا، تو ہم تم سے لڑیں گے ویسے ہی جیسے ہم اسامہ سے لڑ رہے ہیں!‘۔
مغربی دانشگاہوں، میڈیا اور ثقافتی جنگ کے ذریعے، مغرب میں بسنے والے مسلمانوں اورمسلم اکثریتی ممالک میں رہائش پذیر مسلمانوں……دونوں کا اس جنتر منتر سے سابقہ پڑا ۔ اور ان مسلمانوں نے مغرب کی بات پر کان دھرے ۔ وہ جمہوریت پر ایمان لے آئے اور وہ آزادی پر ایمان لائے۔ ان میں سے ایک نے کہا:’جمہوریت ہی ہمارا جہاد ہے‘، اور دوسرے نے کہا:’ہم شریعت سے پہلے آزادی چاہتے ہیں‘۔
بہت سی سیاسی پارٹیاں، چاہے وہ مصری اخوان المسلمون ہو یا تیونس کی النہضۃ، بہت سوں نے اپنی اسلامی میراث کو جمہوریت، سیکولرزم اور لبرلزم کے غیر اسلامی نظریات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی جس سے محض ایک خلط ملط سا ملغوبہ وجود میں ّیاجس کے نتیجے میں مغرب کو خوش و راضی کرنے کی خاطر ان کی اساسی و بنیادی شناخت تک پھیکی و کمزور پڑ گئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، اپنے عقیدے، اپنے منہج اور اپنے نظریے کو تبدیل کیا۔
یہ سب کرنے کے بعد ان کا خیال تھا کہ مغرب انہیں قبول کر لے گا۔ مگر ہوا کیا؟
ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ مصر کی ’رابعہ العدویہ‘ مسجد میں کیا کچھ پیش آیا۔ ہم نے دیکھا کہ تیونس جیسے ممالک میں کیسے مغرب کی پشت پناہی سے جمہوری حکومتوں کو ہٹایا گیا۔ مغرب نے پہلے بھی اِبن زاید سے لے کر سیسی اور ہفتر، ابن سلمان اور قیس سعید تک، بد ترین ظالم و جابر حکمرانوں کی حمایت کی، اور اب تک کرتا چلا آ رہا ہے۔
فلہٰذا ’اسلامی کمیونسٹ‘ اور ’مسلم یا عرب قوم پرستوں‘ جیسے جدّت پسندوں کی طرح ’اسلامی جمہوریت‘ کے علم بردار بھی دھوکہ کھا گئے ۔ مغرب نے ان سے جھوٹ بولا، اور انہیں کٹھ پتلیوں کی طرح اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جیسا کہ اس کی دیرینہ عادت ہے۔
جمہوریت کے ساتھ خبطی قسم کاشدیدلگاؤ کیوں بطورِ خاص حیران کن محسوس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ اس کی سطحیت ہے۔آخر جمہوریت……فی نفسہ …… کیسے مسلم دنیا میں پائے جانے والے اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی مسائل کو حل اور دور کر سکتی ہے؟جمہوریت میں ایسی کون سی صفت یا خصلت ہے جو اسے ایک ہمہ گیر اور جامع سیاسی نظام بناتی ہے جو ان تمام مسائل، جن کی جڑیں گہری اور دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، کا کا فی و شافی حل پیش کر سکے؟
تاریخ اس پر شاہد ہے کہ مغرب کی اٹھان کے پیچھے نوآبادیت و سامراجیت کا ہاتھ تھا۔اقتصادی ترقی اور ٹیکنالوجی کے ارتقا کا جمہوریت سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے۔جمہوریت مسئلے کا ایک جزو ہے، نہ کہ اس کا حل۔
آج کے نام نہاد ’اسلام پسندوں‘…… جو اپنے ایما ن کو جمہوریت اور سیکولر ریاست کے ساتھ نتھی کرتے ہیں…… کو کسی بھی طور ’اسلامی‘ یا اسلام پسند نہیں کہا جا سکتا۔ یقیناً ان کے حامیوں کی اکثریت با عمل مسلمانوں پر مشتمل ہے جو ایسی (اسلام پسند) پارٹیوں اور تحریکوں کی حمایت و نصرت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اسلامی عدل، اخلاق اور رحم کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔
مگر وہ در حقیقت یہ فہم اور ادراک نہیں رکھتے کہ جمہوریت ہے کیا چیز، اور سیکولر ریاست کی اصل طبیعت و فطرت کیا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ قانون سازی پارلیمنٹ کے ممبران کے ہاتھوں ہوگی۔وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جمہوریت میں آئین و دستور اور پارلیمنٹ کو قرآن و سنت پر ترجیح اور فوقیت دی جاتی ہے۔
شریعتِ اسلامی بہر لحاظ جمہوریت اور سیکولر ریاست کے ساتھ ناموافق اور بے جوڑ، بلکہ اس کی متضاد و متناقض ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ شریعت دقیانوسی و نا معقول، غیر منطقی اور موجودہ حالات کے لیے غیر مناسب ہے، بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ جمہوریت، سیکولرزم اور قومی ریاست (مغربی یورپ سے آنے والا ایک خصوصی جدید تصور)کے تصورات اساسی اور بنیادی طور پر ناقص ہیں اور اس اعلیٰ اخلاقی نمونے کی ضد ہیں جو شریعت کہلاتا ہے۔
ریاست اپنے آپ کو اقتدار و اختیارِاعلیٰ تصور کرتی ہے۔ ریاست کا قانون سب سے بلند و برتر ہے۔ اپنی سرحدی حدود کے اندر ریاست سب جاننے والی، ہر جگہ موجود اور ہر شے پر قادر رہنا چاہتی ہے (یعنی ریاست قادرِ مطلق، عالمِ کل اور حاضر و ناظر رہنا چاہتی ہے)۔ جمہوریت کی طرح، سیکولر ریاست کا یہ تصور بھی ایک خدائے باطل سے زیادہ کچھ نہیں، یہ ایک تراشیدہ بت ہے۔
اسلام تو محض ایک خدائے واحد و لاشریک کے سامنے سرِ تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔جو واحد و یکتا ہے، جبّار و قہار ہے ، مالک الملک اللہ ہے۔اور اسلامی نظامِ حکومت قانون کی حکمرانی، اختیارات کی علیحدگی ، کم سے کم حکومت (یعنی عوام کی زندگی میں ریاستی مداخلت) اور معاشرتی ترقی کی کہیں زیادہ کامیاب اور مستحکم صورت فراہم کرتی ہے جو سیکولر ریاست کبھی بھی نہیں کر سکتی۔
اسلامی معاشروں کی ہزار سالہ تاریخ دنیاوی اعتبار سے بھی نہایت معتدل و متوازن، پائیدار اور کامیاب نمونہ پیش کرتی ہے۔اسلامی نظام میں حکمران کی طاقت اور حدودِ اختیار پربنیادی طور پر خود اسلام اور علمائے اسلام نظر رکھتے تھے۔یہ علمائے اسلام ایسے فقہی (قانونی)ماہرین تھے جو کہ مجتمعِ اسلامی ( اسلامی معاشرے) کی اپنی طبعی پیداوار تھے (یہ علماء خودنہایت فطری طریقے سے اسلامی معاشرے ہی سے اٹھنے والے؍ پیدا ہونے والے قانونی ماہرین تھے)۔ وہ قرآن و سنت ، علمی روایات اور اپنے معاشرے سے جڑے ہوئے افراد تھے۔ اگر ان میں سے بعض فاسد بھی ہو گئے (جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اہلِ علم بھٹک جائیں گے) تو بھی ایسے اہلِ علم ہمیشہ موجود رہے اور رہیں گے جو حق پر ثابت قدم رہے۔ لہٰذا کوئی قوّت یا کوئی حکمران بھی یہ اختیار نہیں رکھتا تھا کہ وہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق قانون کو تبدیل کرے یا توڑ مروڑ کر بگاڑے……جیسا کہ جدید سیکولر ریاست میں کیا جاتا ہے۔ علماء کے درمیان پایا جانے والا اختلافِ رائےبھی اس بات کا ضامن تھا کہ اسلام میں رائے کا ایسا افراط موجود رہے جو قانونِ اسلامی کو ہر قسم کی نئی صورتحال کا سامنا کرنے کے قابل بنائے۔
اسلامی نظام کےتحت معاشرہ انتہائی منظّم تھا جسے آسانی سے دستیاب و موجود ، معقول اور قابلِ فہم معیارِ عدل نے جوڑ رکھا تھا۔سیاست اس قدر کم تھی کہ نہ ہونے کے برابر تھی۔حکمران بعض امور کی انجام دہی کے پابند تھے۔ وہ شریعت کی بالادستی قائم کرتے، مسلمانوں کے حقوق اور ان کی عزت کا تحفظ کرتے اور کفر و کفار کے خلاف مسلمانوں کی تلوار اور ان کی ڈھال بنے رہتے۔ اس کے بدلے میں عوام انہیں اپنی بیعت ……یعنی وفاداری کا عہد …… اور شریعت کے مقرر کردہ ٹیکس ادا کرتے۔
اور اس نظام کے تحت ۱۲۰۰ سال تک امتِ مسلمہ پھلتی پھولتی رہی۔ہاں یقیناً بعض اوقات ہم پر زوال بھی آیا، ہم گرے بھی، مگر اللہ کے فضل و کرم سے ہم دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے۔مگر یورپی جارحیت کے بعد سے ہم نے خود اپنی مرضی اور اختیار سے سیکولر ریاست کا نظام اور جمہوریت و لبرلزم کے نظریات اپنا لیے، اور اس آسمانی ہدایت و رحمت کو پسِ پشت ڈال دیا کہ جو اسلامی نظام کہلاتا تھا۔
مستقبل میں کیا ہو گا؟
جمہوریت او رسیکولر قومی ریاست کے بت اب ٹوٹ رہے ہیں۔ آج مغربی دانشور روزانہ کی بنیاد پر ’طاقت کی سیاست کی واپسی ‘ اور’تمدنی ریاستوں‘ کی بحث کرتے ہیں۔
دوسری جنگ ِ عظیم کے بعد سے جو بین الاقوامی نظام قائم تھا، بالخصوص وہ ’یک قطبی عہد‘ جو جمہوریت و لبرلزم پر بے جا اعتماد و یقین کاسبب بنا، اب ختم ہوگیا ہے۔ جیسا کہ یوکرین کی جنگ سے ظاہر ہے، دنیا کا نظام تبدیل ہو رہا ہے۔مجھے یقین ہے کہ آنے والی دہائیوں میں ہم سیاسی، معاشی و معاشرتی……ہر لحاظ سے بہت بڑے اور عظیم انقلابات کا مشاہدہ کریں گے۔ اور بین الاقوامی برادری اور عالمِ کفر کے اکٹھ اقوامِ متحدہ کی بیکار و لاحاصل بحثوں کے بجائے قوت کی سیاست کو لوٹتا دیکھیں گے۔ایک چند قطبی دنیا میں مضبوط و طاقتور اور پر عزم قائدین اپنی سلطنتیں آپ تراشیں گے کیونکہ کسی بھی ایک بلاک (مغرب، چین یا روس) کو ایسی کامل طاقت و اختیار حاصل نہ ہو گا کہ ان معاملات میں اپنی منوا سکے۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو یہ کہیں گے کہ اس کھیل کے اصول بدلنے والے ہیں۔ نہیں ، بلکہ وہ بدل بھی چکے ہیں۔ بقولِ اقبالؒ:
جہانِ نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالَمِ پِیر مر رہا ہے
جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا قمار خانہ
مسلمانوں اور بالخصوص اسلامی تحریکوں کو ضرورت ہے کہ اس نئی حقیقت کو سمجھیں اور اس کے مطابق منصوبہ بندی کریں۔ ان شاء اللہ اس امّت کی فتح پہلے سے کہیں زیادہ قریب تر ہے۔ربّ کعبہ کی قسم! اس میں کوئی شک نہیں کہ امّتِ محمدیہ ﷺہی فتح یاب ہو گی، مگر حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا جائے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوا جائے۔درست حکمتِ عملی بنانےکے لیے ضروری ہے کہ آگے دیکھنے کے ساتھ ساتھ پیچھے بھی دیکھا جائے۔
پہلی اور اوّلین ضرورت اس بات کی ہے کہ جمہوریت اور سیکولر ریاست کے بتوں کو اٹھا پھینکا جائے اور نفاذِ حکومتِ اسلامی کے مقصد و ہدف کو دل سے قبول کیا جائے۔اس کے ساتھ ساتھ ناگزیر ہے کہ اپنی اور معاشرے کی اصلاح کی جدو جہد ہر لمحہ جاری رکھی جائے ، کہ تجدید بغیر اصلاح کے ممکن نہیں۔
دوسری ضرورت یہ ہے کہ قومی ریاستوں اور سرحدوں کی پیدا کی ہوئی اس ذہنی قید سے آزادی و نجات حاصل کی جائےاور پوری امّت کے اعتبار سے سوچا جائے، اس کی قوّتوں اور کمزوریوں کے اعتبار سے ۔
تیسری بات یہ کہ جہاں کہیں ممکن ہو (ان علاقوں میں جنہیں علمائے جہاد نے بنیادی (primary) علاقوں سے تعبیر کیا ہے)، مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا آغاز کریں۔ واللہ! یہی وہ راستہ ہے جو عزت و شرف، قوت اور فتح و کامرانی کی جانب لے جاتا ہے۔
چوتھی بات یہ کہ جن علاقوں میں طاقت کے عدم توازن، زمینی صورتحال یا دیگر وجوہات کی بنا پر فی الحال دشمن کے ساتھ دو بدو مقابلہ ممکن نہ ہو ، وہاں اسلامی تحریکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مندرجہ ذیل طریقے اپنائیں:
- توحید (خصوصاً توحیدِ حاکمیت)کے بارے میں ایک کھلے اور غیر مصالحانہ موقف کی حامل ایک ایسی دعوت (پھیلائی جائے) جو ہر قسم کے کفری نظاموں اور نظریات و تصورات کا ردّ کرنے والی ہو۔
- اپنے خون اور تلوار سے پرچمِ اسلام کو بلند کرنے کی کوشش و سعی میں مصروف مجاہدین کی ہر ممکن طریقے سے مدد و نصرت کی جائے۔
- مقامی طور پر اجتماعی عمل و جدوجہد کے ذریعے معاشرتی و تزویراتی قوّت حاصل کرنے کے طویل سلسلے کو رواں کرنے کی کوشش کی جائے اور ساتھ ساتھ ان نظریات اور اداروں (بشمول سیکولر و قوم پرست سیاسی پارٹیوں اور نعروں) کی بیخ کنی کی جائے جو مسلمان عوام کی آنکھوں پر پردہ ڈالے رکھنے کے کام آتے ہیں۔
- اس آبِ جو کو دریائے تند و تیز میں بدلنے کے درست لمحے کا انتظار کیا جائے۔
طاقت و قوّت بزور حاصل کی جاتی ہے، بخشش میں نہیں ملتی…جو چیز ظاقت کے بل پر غصب کی گئی ہو ، اسے بزورِ طاقت ہی واپس لیا جا سکتا ہے ۔ اور اس امّت کی فتح محض ایک ہی قوّت، ایک ہی طاقت، ایک ہی نظریے کے ذریعے ممکن ہے:……اصل و مستند اسلام……اور ماسوائے اس کے کچھ بھی نہیں۔
واللہ اعلم بالصواب!
٭٭٭٭٭
1 دہریت؍ فلسفۂ طبیعی: یعنی یہ فلسفہ کہ دنیا اور اس میں وقوع پذیر ہونے والی ہر شے کی ما فوق الفطرۃ یا الہامی و دینی اسباب سے صرفِ نظر کرتے ہوئےفطری یا سائنسی بنیادوں پر توضیح ممکن ہے۔