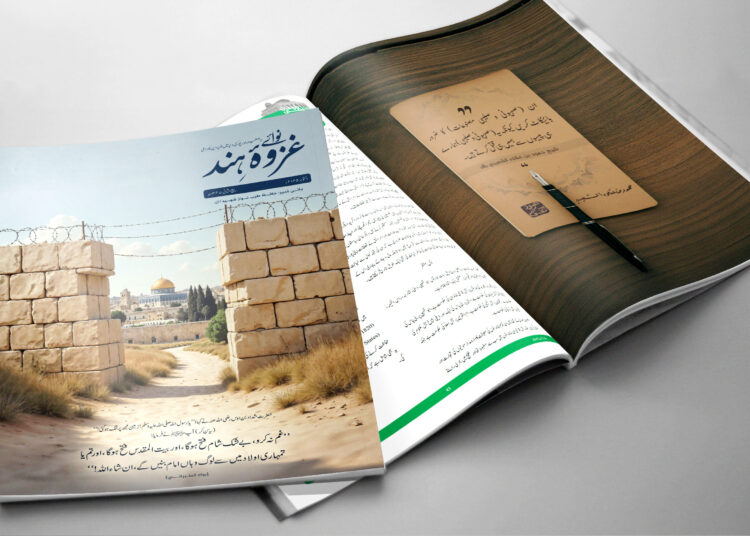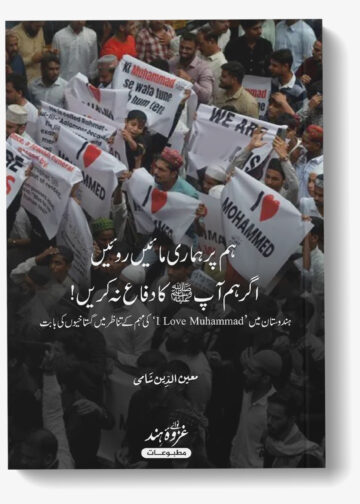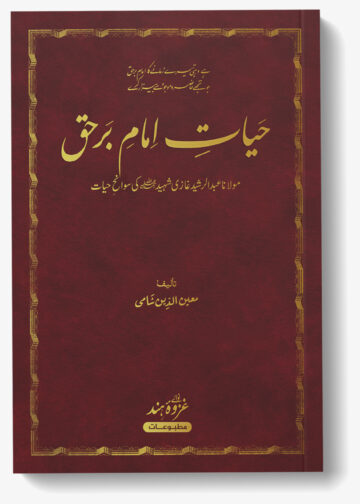يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۗءٌ مِّنْ نِّسَاۗءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۭ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (سورۃ الحجرات: ۱۱)
’’اے ایمان والو! کوئی قوم دوسری قوم کی ہنسی نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں کی ہنسی کریں ، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں ، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور نہ برے ناموں سے پکارو، ایمان کے بعد فسق بدترین نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ناانصاف ہیں ۔‘‘
اصلاح معاشرہ کے قیمتی اصول
قومی عصبیت
موجودہ دور کے فتنوں میں جس فتنہ نے مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کر رکھا ہے وہ فتنہ ’’قومیت‘‘ کا ہے، یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، زمانۂ جاہلیت میں اسی قومیت نے ہزاروں کی جان لی، آدم کی اولاد کو اس نے ٹکڑیوں میں بانٹ دیا، قبائل کی تفصیل و تقسیم اس لیے تھی کہ تعارف وتفاہم کا ذریعہ بنے، لوگوں نے اس کو افتراق کا ذریعہ بنالیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا (سورۃ الحجرات: ۱۳)
’’اور تمہارے خاندان اور برادریاں بنا دیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔‘‘
ایک رب کے بندے اور ایک باپ کی اولاد، لیکن رنگ و نسل نے ان کے شیرازے کو ایسا منتشر کیا کہ وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئے۔
قومی فخر و غرور اس طرح ان کے اندر داخل ہو گیا تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلوں کی سر عام تحقیر و تذلیل کرتا، اپنے باپ دادا کے مفاخر بیان کرنے کے لیے مجلسیں آراستہ کی جاتیں ، اور اس میں دوسروں کی کمزوریاں تلاش کی جاتیں ، اور ان کو کم دکھانے کی کوششیں ہوتیں ، اس کے نتیجہ میں کبھی کبھی بڑی طویل خوں ریز لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور سیکڑوں جانیں تلف ہو جاتیں ، لیکن یہ چیزیں ان کے یہاں کچھ معیوب نہ تھیں ، بلکہ ان کو قومی مشاغل کا اہم حصہ سمجھا جاتا تھا۔
اسلام کی تعلیم
اسلام نے اس جاہلی نخوت اور بے جا فخر و غرور کو توڑا، ارشاد ہوتا ہے:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ
’’اے ایمان والو! کوئی قوم دوسری قوم کی ہنسی نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ (جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے) ان سے بہتر ہوں (جو مذاق اڑانے والے ہیں)۔‘‘
آیت شریفہ میں ہر طرح کے قومی تقدس کی نفی کی جا رہی ہے اور صاف صاف یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وجہ امتیاز کسی قوم کا فرد ہونا نہیں ہے، بلکہ امتیاز کی اصل بنیاد وہ صفات ہیں جو ایمان والے کے لیے قرب الٰہی کا ذریعہ ہیں، خیر کا انحصار اسی پر ہے، فضل و کمال کسی قوم کی جاگیر نہیں ہے بلکہ یہ وہ صفات ہیں جو محنت و جستجو کے بعد توفیقِ الٰہی سے حاصل ہوتی ہیں ، اور ان میں بہت سی باطنی کیفیات اور اندرونی حالات وہ ہیں جو ظاہر بین اپنی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا، تاہم ہر آدمی اپنی کمزوریوں سے بخوبی واقف ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے لیے کہاں جواز رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں اور اپنی قوم کے بارے میں بڑائی کے احساس میں مبتلا ہو، اور دوسروں کو حقیر سمجھے، اسی لیے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اس کی ممانعت کر دی گئی کہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور اس کی نفسیاتی وجہ بھی بیان کر دی گئی کہ وہ اپنی بڑائی کے احساس کی جس بنیاد کو لے کر یہ عمل کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ بنیاد ہی کھوکھلی ہو۔
یہاں لفظ ’’قوم‘‘ کا استعمال ہوا ہے، اس کے مفہوم میں خاندان اور قبیلہ بھی داخل ہے، جماعت اور گروہ بھی شامل ہے، اور ظاہر ہے جب قبیلہ خاندان اور جماعت کو اس سے روکا جا رہا ہے کہ وہ کسی دوسرے خاندان، جماعت یا گروہ کی تحقیر کریں تو کسی ایک فرد کو اس کی اجازت کہاں حاصل ہ وسکتی ہے۔
خاص طور پر ’’قوم‘‘ کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ زمانۂ جاہلیت کا خاص مرض تھا جس میں وہ مبتلا تھے، جب اخوت اسلامی کی لڑی میں ان کو پرو دیا گیا تو اب نسل و قوم کی تفریق کہاں باقی رہ سکتی تھی، اس کے مفہوم میں فرد واحد بھی داخل ہے، آیت کی رو سے کسی کو بھی وہ فرد ہو یا جماعت ہو یا قبیلہ، اس کا جواز نہیں ہے کہ وہ دوسروں کا مذاق اڑائے۔
آیت کے شانِ نزول میں ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ بنوتمیم کے کچھ لوگوں نے ایک موقع پر ان حضراتِ صحابہؓ کی تحقیر کی تھی، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، حضرت بلال حبشیؓ، حضرت صہیب رومیؓ، حضرت سلمان فارسیؓ، جو سب کے سب دوسرے ملکوں کے تھے، قبائل عرب میں ان کو کوئی خاندانی شناخت نہیں تھی، ان کو نامناسب کلمات کہہ دئیے گئے تھے، اس پر آیت شریفہ میں تنبیہ کی گئی اور سختی سے روک دیا گیا۔1
خواتین سے خطاب
گرچہ ’’قوم‘‘ میں خواتین بھی شامل ہیں ، اور ممانعت عام ہے، لیکن چونکہ خواتین میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی فاسد ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، اس لیے ان کے بارے میں مستقل وہی بات دہرائی جارہی ہے، ارشاد ہوتا ہے:
وَلَا نِسَاۗءٌ مِّنْ نِّسَاۗءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ
’اور نہ عورتیں عورتوں کی ہنسی کریں ، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں ۔‘‘
آیت کا یہ حصہ خواتین کے لیے خاص طور پر قابل غور ہے، سماج میں بگاڑ کا ایک بڑا سبب ان کی بے احتیاطی ہے، جس طرح مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صنف نازک کا خیال رکھیں، آنحضرت ﷺ نے ایک سفر کے موقع پر فرمایا تھا:
رفقاً بالقواریر2
’’ان آبگینوں کا خیال رکھو، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔‘‘
آپ ﷺسے بڑھ کر عورتوں کو حق دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح عورتوں کو بھی اس کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ خود بھی حق شناس اور احسان شناس بنیں ، ایک حدیث میں ان کے جہنم میں جانے کے دو بنیادی اسباب بیان کیے گئے ہیں ، ایک طعن کی کثرت اور دوسرے شوہروں کی احسان نا شناسی۔3
آیت شریفہ میں بھی بطور خاص عورتوں کو اسی کی تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، اور یہ بات تو کس قدر بے شرمی اور بے احتیاطی کی ہے کہ وہ مردوں کا مذاق بنائیں ، اگر وہ شوہر یا باپ ہے تو یہ احسان ناشناسی کی انتہا ہے اور اگر غیر ہے تو بے احتیاطی کے ساتھ بے حیائی بھی ہے۔
’’لمز‘‘
اسی آیت شریفہ میں دوسری جس چیز کی ممانعت کی جا رہی ہے وہ ’’لَمْز‘‘ ہے، ’’لَمْز‘‘ ہر اس کلام یا اشارہ کو کہتے ہیں جس میں مخاطب کی مذمت کی جا رہی ہو، چِڑھایا جا رہا ہو، او ر ڈرایا دھمکایا جا رہا ہو، کہنے والا جس چیز کو خود معیوب سمجھتا ہو، وہ اس چیز کو مخاطب کی طرف منسوب کرے، وہ عیب مخاطب کے اندر موجود ہو تو بھی اس کا تذکرہ درست نہیں ہے اور وہ عیب مخاطب کے اندر موجود نہ ہو تب تو اس گناہ کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی عیب کو کسی کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ بھی اس عیب میں مبتلا نہ کر دیا جائے4، لمز کی ممانعت کے لیے جو تعبیر استعمال ہوئی ہے وہ بھی نہایت بلیغ ہے، ارشاد ہوتا:
وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ
’’اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ ۔‘‘
أنفس، نفس کی جمع ہے، لغوی معنی یہ ہیں کہ اپنی جانوں کو برا مت کہو، اس کے نتیجہ میں تم کو بھی برا کہا جائے گا، دوسرا اشارہ اس میں یہ ہے کہ تم جن ایمان والے بھائیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو، وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارا ہی حصہ ہیں ، ان کو الگ مت سمجھو، ان کو برا بھلا کہنا خود اپنی ذات کو برا کہنا ہے۔
برے ناموں سے پکارنا
تیسری جس چیز سے روکا جارہا ہے وہ برے ناموں سے پکارنا ہے، فرمایا جارہا ہے:
وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ
’’اور نہ برے ناموں سے پکارو۔‘‘
جن القاب کو معیوب سمجھا جاتا ہو، ان سے احتیاط کرنی چاہیے، القاب کبھی خلقی نقص کی بنا پر پڑ جاتے ہیں ، جیسے اندھا، کانا، بہرا، نکٹا وغیرہ، ظاہر ہے جس کو ان ناموں سے پکارا جائے گا اس کو کس قدر تکلیف ہو گی، کبھی بری عادتوں کی وجہ سے نام پڑ جاتے ہیں ، کسی نے چوری کی، اس کو چور کہا جانے لگا، وہ تائب ہو گیا، پرہیز گار بن گیا، تب بھی اس کو چور کہا جا رہا ہے، کوئی بھی ایسا لقب یا نام جس سے مخاطب تکلیف محسوس کرے، اس سے بچنا چاہیے، حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔5کسی بھی قول سے، فعل سے، طرز گفتگو سے تکلیف پہنچ سکتی ہو، اس سے بچنا ضروری ہے۔
بندوں کے حقوق
یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک حق اللہ کا ہے اور دوسرا حق بندوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ پسند فرماتے ہیں ، اپنے حق میں وہ معاف فرما دیں گے، لیکن بندوں کا حق اس وقت تک معاف ہونا مشکل ہے جب تک معاف نہ کرا لیا جائے۔ اگر گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس گناہ کی توبہ قبول ہی اس وقت ہو گی جب حق ادا ہو جائے یا اس کی معافی کرائی جائے۔ یہ توبہ کے شرائط میں سے ہے۔
ہمارے معاشرے کا یہ سب سے بڑا مرض ہے جو ہم مسلمانوں کو گھُن کی طرح لگ گیا ہے، بالائے ستم یہ کہ اس کو مرض نہیں سمجھا جاتا، اچھے اچھے دیندار لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس سے مسلمانوں کی بہت غلط تصویر انسانی سماج میں جا رہی ہے، اخلاقیات اور معاملات میں کھوکھلا پن بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے یہ بڑا لمحۂ فکریہ ہے، اس کی اصلاح کی شدید ضرورت ہے، تاکہ اسلامی معاشرہ مکمل اسلام کی تصویر بن سکے۔
جب آیت شریفہ میں استہزا کرنے، برا بھلا کہنے اور برے ناموں سے پکارنے کی ممانعت ہے تو حق مارنا کس درجہ گناہ کی بات ہوگی، ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے صحابہؓ سے پوچھا: جانتے ہو مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں ۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مفلس وہ نہیں ہے (جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو) مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو ستایا ہو گا، کسی کا حق مارا ہو گا، کسی کو گالی دی ہو گی، ان تمام لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی برائیاں اس کے سر ڈالی جائیں گی، اور پھر (ہزاروں نیکیوں کے باوجود) اس کو منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔6
زبان کی خرابیاں
زبان کا استعمال آدمی آسانی سے کر لیتا ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس سے کتنے دل دکھے، کتنوں پر زد پڑی، کہاں کہاں معاملات بنتے بنتے بگڑ گئے، آیت شریفہ میں جن باتوں سے روکا جا رہا ہے، ان میں زیادہ تر زبان کی بے احتیاطیاں اور برائیاں ہیں ، اس کی وجہ یہی ہے کہ زبان کے استعمال میں آدمی کو باک نہیں ہوتا، وہ اکثر سوچ ہی نہیں پاتا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی بعض مرتبہ دیکھنے میں معمولی سی بات زبان سے نکالتا ہے، وہ اس کو تحت الثّریٰ میں پہنچا دیتی ہے، معاشرہ کے بگاڑ میں زبان کا سب سے بڑا دخل ہے، بعض مرتبہ اس کا گھاؤ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اس کا بھرنا آسان نہیں ہوتا، ایک عرب شاعر کہتا ہے:
جراحات السنان لھا التیام
ولا یلتام ما جرح اللسان
’’نیزوں کے زخم بھرے جاسکتے ہیں ،
لیکن جو زخم زبان سے لگتا ہے وہ بھرا نہیں جاسکتا۔‘‘
زبان کے بے جا استعمال سے آدمی خود مصیبت مول لیتا ہے، عمومی طور پر پریشانیوں کا سبب یہی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف صاف فرماتے ہیں:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا (سورۃ الأحزاب: ۷۰، ۷۱)
’’اے ایمان والو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اور جچی تلی بات کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو بنا دے گا اور گناہوں کو معاف کر دے گا۔‘‘
ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم دو چیزوں کی ضمانت لے لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں:
الفم والفرج7
’’منہ اور شرم گاہ۔‘‘
ایک دوسری حدیث میں فرمایا:
وھل یکبّ الناس علی وجوھھم إلا حصائد ألسنتھم8
’’لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل ان کی زبان کے کرتوت ہی لے جائیں گے۔‘‘
حدیث کی یہ نہایت ہی بلیغ تعبیر ہے، حصیدۃ کی جمع حصائدہے، حصائد کٹی ہوئی کھیتی کو کہتے ہیں ، درانتی یا ہنسیا سے جب کھیتی کاٹی جاتی ہے، تو غلہ کے ساتھ جنگلی گھاس بھی اس میں آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیڑے مکوڑے بھی درمیان میں پھنس کر کٹ جاتے ہیں، کاٹنے والا اپنا عمل جاری رکھتا ہے، یہی زبان کا حال ہوتا ہے، جو لوگ بغیر دیکھے بھالے، سوچے سمجھے، اس کا استعمال کرتے ہیں ، وہ بعض فائدوں کے ساتھ اپنا کتنا نقصان کر لیتے ہیں، اس کا اندازہ ان کو نتائج نکلنے کے بعد ہوتا ہے، اور بہت سے نتائج تو آخرت پر موقوف ہیں ، اسی لیے قرآن و حدیث میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے کہ زبان کا استعمال احتیاط کے ساتھ کیا جائے، ایک حدیث میں آتا ہے:
من کان یؤمن باﷲ والیوم الآخر فیلقل خیرا أو لیصمت9
’’جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔‘‘
ہزار خرابیوں کی جڑ یہ زبان ہے، آدمی بعض مرتبہ کچھ نہیں تو اپنی تعریف ہی شروع کر دیتا ہے، اور اس کے اندر تعلّی کا احساس شامل ہو جاتا ہے، جو اس کو نقصان پہنچاتا ہے، حاصل یہ ہے کہ تحفظ کے ساتھ زبان کا استعمال ہو گا تو بچنے کی امید ہے، ورنہ خطرہ ہی خطرہ ہے، آیت شریفہ میں اسی لیے بڑی تاکید کے ساتھ یہ احکامات دیے گئے ہیں تاکہ زبان سے کوئی تکلیف کسی کو نہ پہنچے۔
بدترین بات
فسق اللہ کے حکم سے سرتابی کو کہتے ہیں ، زبان کے غلط استعمال سے ممانعت کے بعد ارشاد ہوتا ہے:
بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ
’’ایمان کے بعد فسق بدترین نام ہے۔‘‘
اس میں صاف صاف یہ اشارہ ہے کہ اوپر جن منہیات کا ذکر تھا وہ سب فسق میں شامل ہیں ، ایک حدیث میں آتا ہے:
سباب المؤمن فسوق10
’’مومن کو گالی دینا فسق کی بات ہے۔‘‘
اسم اپنے مسمّٰی پر دلالت کرتا ہے، جہاں کسی چیز کا نام لیا جاتا ہے، وہاں اس کا چرچا ہوتا ہے، اس میں بظاہر یہ اشارہ ہے کہ ایمان کے ٹھپہ لگ جانے کے بعد لوگوں میں اس کا چرچا ہو جانے کے بعد پھر فسق کا چرچا ہو، یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، اور اس سے اسلام پر زد پڑتی ہے، عام لوگ فرق نہیں کر پاتے، جب وہ مسلمان میں کسی صفت کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، کسی مسلمان کے فعل سے اسلام پر زد پڑے اور اس کا یہ عمل دعوت اسلام کے لیے روڑا بنے، اس سے بڑھ کر برائی کیا ہو سکتی ہے؟
اور پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے سرفراز فرمایا، اخلاق کی بلندی عطا فرمائی، ایسی پاکیزہ تعلیمات دیں جو نہ کسی مذہب میں مل سکتی ہیں اور نہ کسی تہذیب میں، اس کے بعد پھر آدمی سرتابی کرے، ان تعلیمات کی ناقدری کرے، تو یہ بدترین بات ہے، ترقی کے بعد تنزلی، روشنی کے بعد تاریکی، علم کے بعد جہالت، ایمان کے بعد فسق و فجور، اس کو سوائے بے توفیقی کے اور کس چیز سے تعبیر کیا جائے، آپ ﷺ نے جن چیزوں سے پناہ مانگی، ان میں یہ بھی ہے:
أعوذ بک من الحور بعد الکور11
’’اے اللہ تاج سعادت دے کر پھر اس سے محروم نہ فرمانا۔‘‘
’’کور‘‘عمامہ کے پیچ کو کہتے ہیں ، اور ’’حور‘‘ اس کے کھل جانے کو کہتے ہیں ۔
توبہ کی قیمت
بڑے سے بڑے سرکش، کافر اور گنہگار کے لیے بھی اللہ نے دروازہ بند نہیں کیا، جب تک جان میں جان ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر ان ہزار خرابیوں کے بعد بھی بندہ مالک کی طرف لوٹ جائے، توبہ کر لے ، تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کردیتے ہیں:
اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (سورۃ الزمر: ۵۳)
’’وہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔‘‘
ہاں اگر کوئی عناد پر کمربستہ ہے اور رجوع نہ کرے تو اس کے بارے میں ارشاد ہے:
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ
’’اور جو توبہ نہ کریں وہی ناانصاف ہیں ۔‘‘
کوتاہی کا احساس بڑی چیز ہے، اپنی غلطی کو غلطی سمجھنا معمولی بات نہیں، غلط راستہ پر پڑ جانے کے بعد اگر اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا تو آدمی واپس آ سکتا ہے، صبح کا بھولا شام کو اگر گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، لیکن اگر راستہ بھٹک جانے کے بعد احساس ہی نہ رہے تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جائے، اور پھر اس کو منزل ہی نہ مل سکے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو تو بہ نہیں کرتا وہی ناانصاف ہے، نہ اس نے اپنے حق کو سمجھا اور نہ دوسروں کے حق کا احساس رہا، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ظالم تو یہی لوگ ہیں ۔
علماء نے توبہ کی تین بنیادی شرطیں کتاب وسنت کی روشنی میں بیان کی ہیں :
- گناہ فوراً چھوڑ دے۔
- احساس ندامت پیدا ہو۔
- دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔
جو گناہ حقوق العباد سے متعلق ہیں ، ان میں چوتھی شرط بھی ضروری ہے کہ اگر اس نے حق ادا نہیں کیا ہے تو ادا کرے، مثلاً کسی کی امانت اس کے پاس ہے، امانت رکھنے والا تقاضہ کر رہا ہے تو بغیر تاخیر کے ادا کر دے، میراث میں کسی اور کا بھی حق رہا ہے تو حساب لگا کر اس کا حصہ اس کو دیدے، کاروبار میں اگر شرکت ہے تو ہر شریک کو اس کا حق ملنا چاہیے، غرض ایک پیسہ بھی اگر دوسرے کا اپنے مال میں شامل ہو گیا تو وہ گویا قطرۂ نجس ہے جو پورے مال کو نجس کر رہا ہے، جتنی جلد ممکن ہو اس کو صاحبِ حق تک پہنچا کر اپنے مال کو پاک کر لیا جائے۔
(جاری ہے، ان شاء اللہ)
٭٭٭٭٭
1 حضرت ابن ابی حاتم نے سورۂ حجرات کی تفسیر میں حضرت مقاتل سے روایت کیا ہے۔
2 مسند الحمیدی بحوالہ مسند انس بن مالکؓ
3 صحیح بخاری، باب کفران العشیر، نسائی، باب قدرالقراء ۃ فی صلاۃ
4 ترمذی، ابواب صفۃ القیامۃ، باب من عیّر أخاہ بذنب، بیہقی ،شعب الایمان
5 بیہقی، شعب الایمان
6 صحیح مسلم، باب تحریم الظلم، ترمذی، باب ماجاء فی شأن الحساب
7 صحیح بخاری، باب حفظ اللسان، شعب الایمان اور مسند احمد کی روایتوں میں چھ چیزوں کا تذکرہ ہے۔
8 ابن ماجہ، باب کف اللسان فی الفتنہ، ترمذی، باب ماجاء فی حرمۃ الصلوٰۃ
9 صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب حفظ اللسان و باب اکرام الضیف، صحیح مسلم، کتاب الایمان باب الحثّ علی اکرام الضیف
10 مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ
11 ترمذی، باب مایقول إذا خرج مسافر، نسائی، باب الاستعاذۃ من الحور