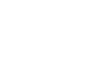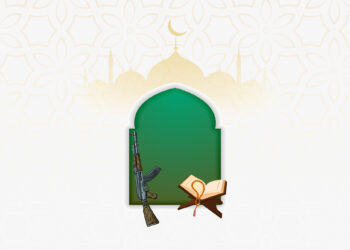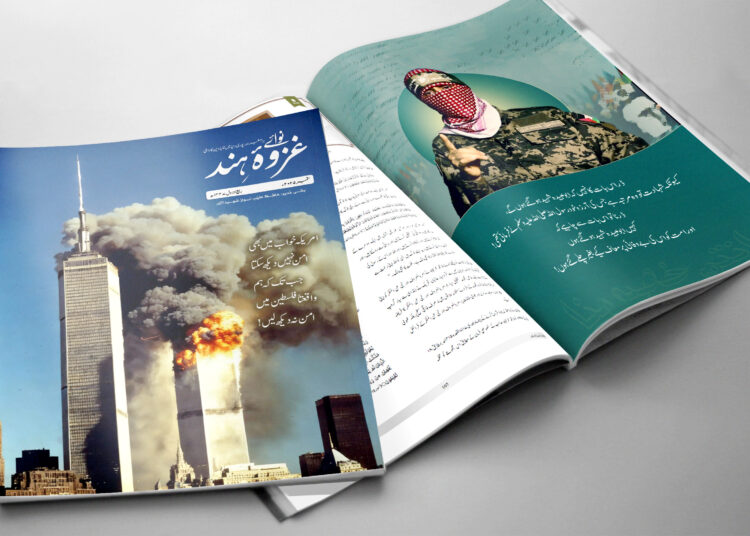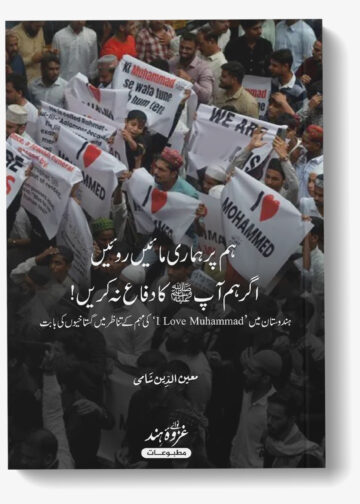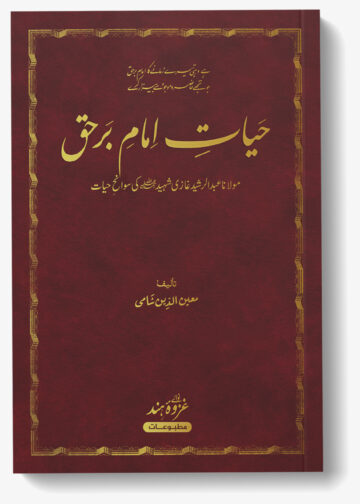مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب (زید مجدہٗ) کی تالیف ’أصول الغزو الفکري‘ یعنی ’نظریاتی جنگ کے اصول‘، نذرِ قارئین ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو اہل باطل کی جانب سے ایک ہمہ گیر اور نہایت تند و تیز فکری و نظریاتی یلغار کا سامنا ہے۔ اس یلغار کے مقابلے کے لیے ’الغزو الفکری‘ کو دینی و عصری درس گاہوں کے نصاب میں شامل کرنا از حد ضروری ہوچکا ہے۔دینی و عصری درس گاہوں میں اس مضمون کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ ’الغزو الفکری‘ یعنی نظریاتی جنگ کے مضمون و عنوان کو معاشرے کے فعال طبقات خصوصاً اہلِ قلم، اسلامی ادیبوں اور شاعروں، اہلِ دانش، صحافیوں، پیشہ ور (پروفیشنل)حضرات نیز معاشرے کہ ہر مؤثر طبقے میں بھی عام کرنا از حد ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے ’اصول الغزو الفکری‘کے عنوان سے اس علم کے اہم مباحث کو مختصر طور پر مولانا موصوف نے پیش کیا ہے۔ مولانا موصوف ہی کے الفاظ میں ’در حقیقت یہ اس موضوع پر تحریر کردہ درجنوں تصانیف کا خلاصہ ہے جس ميں پاک و ہند کے پس منظر کا نسبتاً زیادہ خیال رکھا گیا ہے‘۔ یہ تحریر اصلاً نصابی انداز میں لکھی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود خشکی سے پاک ہے اور متوسط درجۂ فہم والے کے لیے بھی سمجھنا آسان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو نظریاتی و عسکری محاذوں کو سمجھنے، ان محاذوں کے لیے اعداد و تیاری کرنے اور پھر ہر محاذ پر اہلِ باطل کے خلاف ڈٹنے کی توفیق ملے۔ اللہ پاک مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب کو جزائے خیر سے نوازیں کہ انہوں نے ایسے اہم موضوع کے متعلق قلم اٹھایا، اللہ پاک انہیں اور ہم سب اہلِ ایمان کو حق پر ثبات اور دین کا صحیح فہم عطا فرمائیں، آمین یا ربّ العالمین! (ادارہ)
نظریات:
مادّی فلسفے کا حملہ:
فلسفے نے عیسائیت کے ساتھ مل کر موجودہ دور کی اکثر نظریاتی گمراہیوں کو پیدا کیا ہے اس لیے تنقیدی نگاہ سے فلسفۂ یونان کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔
فلسفے کی تعریف:
’فلسفہ‘ ( Philosophy) کے لغوی معنی ہیں ’’حکمت سے محبت رکھنا‘‘۔
اصطلاحی تعریف یہ ہے؛ ’’فلسفہ وہ علم ہے جس سے موجودات کے حقیقی احوال معلوم ہوں‘‘۔
فلسفے کا مقصد عقائد، اخلاق، شہری زندگی، سیاست اور طبعی علوم میں انسان کی رہنمائی کرنا ہے۔ فلسفے کا سارا مدار عقل پر رہا ہے۔ اس نے کبھی وحی سے مدد لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ فلسفہ نہ صرف خیروشر کا معیار خود قائم کرتا ہے بلکہ مابعد الطبعیات(غیب) کے بارے میں بھی وہ خود ہی صحیح یا غلط کے فیصلے کرتا ہے۔
فلسفے کی تاریخ:
اپنی ابتدا سے لے کر اب تک فلسفہ سات ادوار سے گزر چکا ہے۔ جبکہ آٹھواں دور اب جاری ہے۔
۱۔ یونانی دور (سات صدی قبل از مسیح)
۲۔ رومی دور (پہلی صدی عیسوی تا پانچویں صدی عیسوی)
۳۔ عیسوی دور یا ازمنۂ وسطیٰ (پانچویں صدی عیسوی تا پندرہویں صدی عیسوی)
۴۔ احیائے علوم کا دور۔ اصلاح مذہب کی تحریک (پرسٹنٹ مذہب) (پندرہویں صدی عیسوی کا وسط)
۵۔ خالص عقلیت کا دور (وسطِ سترہویں صدی تا اٹھارہویں صدی کا اختتام)
۶۔ صنعتی انقلاب کا دور( ۱۸۰۱ء سے پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک)
۷۔ جھوٹے ادیان کے ایجاد کا دور (پہلی جنگ عظیم کے خاتمے سے ۱۹۹۰ء تک)
۸۔ عالم اسلام کی نشأۃ ثانیہ کے آثار اور اکیسویں صدی
۱۔ یونانی دور:
یونان فلسفے کا گہوارہ مانا جاتا ہے۔ عہدِ قدیم میں یہاں کے لوگوں کے اذہان پر دیوی دیوتاؤں کی اجارہ داری تھی۔ سات صدی قبل از مسیح یہاں حکماء کا ظہور ہوا جو فلسفۂ یونان کے بانی تھے۔ انہیں حکمائے متقدمین کہا جاتا ہے جن میں فیثاغورث (۴۳۶ ق م) اور اس کا شاگرد بقراط (۴۶۹ ق م) بہت مشہور ہیں۔
چوتھی صدی قبل مسیح میں فلسفہ اتنا غالب آگیا کہ دیومالائی ازم کی اہمیت کم ہونے لگی۔ اس دور کے فلسفیوں کو حکمائے متاخرین کہا جاتا ہے۔ یہ یونانی فلسفے کے عروج کا دور تھا۔ سقراط، افلاطون، اور ارسطو اس دور کے نامور فلاسفہ ہیں۔ انھیں فلاسفۂ مشائیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چل پھر کر سبق پڑھاتے تھے۔ فلاسفہ کا دوسرا نامور گروہ اشراقیہ ہے جو اسکندریہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مراقبے اور گیان دھیان کے عادی تھے۔ تیسرا گروہ سفسطائیہ ہے جو اشیاء کے حقائق کا انکار کرتا تھا، اس کے نظریات کی بنیاد وہم پر تھی۔
فلسفیوں کی گمراہیاں:
’وحی‘ سے محروم رہ کر حکمائے یونان گمراہیوں کی انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ عقائد میں جہالت کا یہ حال تھا کہ وہ توحید کی حقیقت سے ناواقف تھے۔ اللہ کی صفات اور پاکی سے لاعلم تھے۔ مادے کو ازلی و ابدی مانتے تھے۔ انھوں نے عقول عشرہ کا تصور دیوی دیوتاؤں سے اخذ کیا اور اسے خالق تعالیٰ پر تھوپ دیا۔
فلاسفہ نے جو طرزِ حیات تجویز کیا اس کا سارا زور فانی دنیا پر تھا۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتےتھے کہ ہم کیسے اور کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے؟ جب مبدأ اور معاد فراموش ہوگئے اور انسانی معاشرہ ہی توجہ کا مرکز بن گیا تو یہاں سے انسانیت پرستی کی سوچ نے جنم لیا، اور ہر مسئلہ پر صرف انسان کے دنیاوی مفاد کے نقطۂ نظر سے غور ہونے لگا۔ اسی سے بعد میں پندرہویں اور سولہویں صدی میں ’انسانیت پرستی‘ (Humanism) کی تحریک کا آغاز ہوا۔
اخلاقیات میں خوش کلامی، خوش اطواری، ادب و تہذیب اور اچھے انداز و اطوار ہی کو کمال سمجھ لیا گیا۔ کبر، حسد، نفاق، حب دنیا اور حب مال و جاہ جو قلب کی تمام بیماریوں کی بنیاد ہیں ان کی سمجھ سے باہر رہے۔ یونانی معاشرے کی سوچ کا محور یہ تھا کہ عدل و انصاف، حسن وجمال اور تمام خوبیوں پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کا واحد ذریعہ انسانی عقل کی تدبیر اور اس کا صحیح استعمال ہے۔ اس معاشرے میں برہنہ جسم کو حسن کامل مانا جاتا تھا اور فحاشی و بے حیائی عروج پر تھی۔
۲۔ رومی دور
فلسفے کا دوسرا دور وہ ہے جب رومی یورپ کی سب سے بڑی طاقت بن کر چھاگئے اور یونان کے ایشیائی مقبوضات پر بھی ان کا قبضہ ہوگیا۔ یہ زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے ۶۴ برس قبل سے شروع ہوکر تیسری صدی عیسوی تک چلتا ہے۔ رومی چونکہ پیشہ ور فوجی اور تلوار کے دھنی تھے اس لیے اس دور میں یونانیوں کی طرح حسن و جمال کی پرستش عام نہ رہی بلکہ طاقت کو اصل چیز سمجھا جانے لگا۔ طاقت کے اسی نشے نے خدا سے مناجات اور تعلق کو بے کار قرار دے دیا۔ طاقت اور قوت میں اضافے کے لیے رومی سلطنت میں وطنیت کا پرچار پاگیا اور اسے رعایا کے اتحاد اور مملکت کی قوت کا ذریعہ بنایا گیا۔
۳۔ ازمنۂ وسطیٰ: عیسوی دور
سلطنتِ روما کے زوال سے تحریک احیائے علوم تک ایک ہزار سال کے عرصے کو قرون وسطیٰ یا تاریک دور کہا جاتا ہے۔ اس دوران فلسفے کی تعلیم پس پشت چلی گئی اور مذہبی علم ہی قدر و منزلت کا ذریعہ قرار پایا۔
۴۔ تحریک احیائے علوم یا نشأۃ ثانیہ کا دور:(Renaissance)
یہ تحریک قرون وسطی کے ’تاریک دور‘ کا اختتام اور ایک نئے دور کا آغاز تھی جس میں انسان نے مذہب سے چھٹکارا حاصل کرکے اپنی خواہشات کے لیے ہر ممکن آزادی پانے کو کوشش کی۔ اس تحریک کے کئی عوامل تھے مثلاً صلیبی جنگوں میں عیسائیت کی شکست، عیسائی مذہب کی اپنی کمزوریاں، یہ احساس کہ عیسائیت معاشرے کی صحیح رہنمائی کرنے سے قاصر ہے، پادریوں کی بدعنوانی و بدکرداری، یورپ میں اسلامی دنیا کے عقلی علوم کی طرف رجوع، آکسفورڈ اور کیمبرج جیسے اداروں کا قیام۔ سب سے بڑا سبب ۱۴۵۳ء میں ترکوں کے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد وہاں آباد یونانی علماء اور فلاسفر کی یورپ میں نقل مکانی تھا۔ ان فلاسفہ کے اثرات کی وجہ سے ایک صدی کے اندر اندر یورپ میں دوبارہ یونانی افکار غالب آگئے۔ احیائے علوم اور ’نشأۃ ثانیہ‘ کی اس تحریک نے مذہبی علوم کو معاشرے کے لیے بے فائدہ قرار دے دیا اور ان کی جگہ عقلیت پسندی اور انسان پرستی کو اختیار کیا جس کی دعوت یونانی فلسفہ دیتا ہے۔
۵۔ عقلیت پسندی کا دور:(Rationalism)
مغربی فلسفے کا پانچواں دور سترہویں صدی کے اواخر سے لے کر ۱۷۷۵ء تک چلا۔ اس دور میں فلسفہ یونانی فلسفیوں کی تنقید سے بھی آزاد ہوگیا۔ عقلیت پسندی کے سب سے نامور علمبردار ’ڈے کارٹ‘ (۱۵۹۶ء تا۱۶۵۰ء) نے فطرت یا خدا کی قدرت کو ایک مشین قرار دیا اور اس کی روحانیت کی حیثیت کا انکار کیا۔ ڈے کارٹ کا سب سے بڑا گمراہ کن نظریہ یہ تھا کہ ’’انسان کے لیے اپنی ذات کے سوا کائنات کی ہر شے میں شک و شبہے کی گنجائش ہے‘‘۔
عقلیت پسندی کے اگلے مرحلے میں صداقت یا حق کے وجود سے ہی انکار کردیا گیا۔ فرانس کے مفکر ’مون ٹین‘ (Montaigne) نے کہا کہ بچپن میں مجھے ککڑی بہت پسند تھی، مگر اب پسند نہیں آتی، اس مثال سے اس نے سمجھایا کہ حق یا صداقت کوئی پختہ اور مستقل چیز نہیں، بلکہ یہ ایک نسبتی شے ہے جو وقت اور مقام کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔
اٹھارہویں صدی کے انگریز فلسفی ’ہیوم‘(۱۷۱۱ء تا ۱۷۷۶ء) نے تمام مذہبی معتقدات کو اس بناء پر مسترد کردیا کہ انہیں نہ تو سائنسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے، نہ وہ عقلی پیمانے پر پورے اترتے ہیں۔
تحریک احیائے علوم اور خالص عقلیت پسندی پر مبنی فلسفے نے مغربی دنیا میں مذہب اور سیاست دونوں کو بہت متاثر کیا۔ مذہبی سطح پر سب سے بڑی یہ تبدیلی آئی کہ اصلاح مذہب کی تحریک شروع ہوگئی جس نے کلیسا کی بالادستی ختم کردی۔
سیاست میں یہ تبدیلی آئی کہ بادشاہ پوپ کی عالمگیر مذہبی حکومت سے نکل کر آزاد ہوگئے۔ قومی حکومتیں وجود میں آئیں اور وطنی تعصب زندہ ہوا۔ اٹلی کے مشہور مفکر ’میکاولی‘ (۱۴۶۹ء تا ۱۵۳۲ء) نے سیاست کے نئے اصول پیش کرتے ہوئے باشاہوں کے لیے دھوکہ بازی اور مکر وفریب کو لازمی اور بادشاہ کی ذات کو ہر باز پرس سے بالاتر قرار دیا۔
۶۔ صنعتی انقلاب کا دور
انیسویں صدی میں صنعتی انقلاب اور مشینی ایجادات نے آخرت کے منکروں کر جیتے جی جنت میں پہنچا دیا۔ یہ سب طبعی سائنس پر دیوانہ وار محنت کا نتیجہ تھا۔ اس اقتصادی ترقی نے معاشرے کو بے شمار نئے مسائل سے دوچار کیا جن کو حل کرنے کے لئے نئے معاشرتی اور سیاسی تصوارت اور نظام پیش کیے گئے۔
۷۔ بیسویں صدی: نفاق اور جھوٹے ادیان کا دور
یہ نفاق، جھوٹے ادیان اور جھوٹی روایتوں کی صدی ثابت ہوئی، اس میں مختلف رجحانات اور افکار کسی قسم کی درجہ بندی کے بغیر نظر آتے ہیں اور باہمی تضادات کے باوجود بیک وقت موجود رہے۔ لوگ نظریاتی ادل بدل کے عادی ہوگئے۔ دو بالکل مختلف اطراف میں بھی کام کرنا ایک عام بات بن گئی۔ اس صدی کے دو مشہور فلسفے یہ ہیں:
فلسفۂ عملیت(Pragmatism)
اس نظریے کے مطابق ’’کوئی خیال یا نظریہ بذات خود صحیح یا غلط نہیں ہوتا، بلکہ ہر خیال کی قدر و قیمت کا فیصلہ عملی یعنی مادی زندگی میں اس کے اثرات اور نتائج دیکھ کر کیا جائے گا‘‘۔
منطقی ثبوتیت(Logical Positivism)
اس کا حاصل یہ ہے کہ ’’اسم کسی چیز پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ ہر لفظ اور جملہ کسی مخصوص حالت (Situation) میں بولا جاتا ہے، چنانچہ جملے میں معنی ڈھونڈنے کے بجائے ہمیں اس حالت کا تجزیہ کرنا چاہیے جس میں یہ جملہ بولا گیا ہے‘‘۔
منطقی ثبوتیت کے قائلین کا کہنا ہے کہ جملے سے کچھ ثابت نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کا پس منظر نہ دیکھا جائے۔ مقصود یہ ہے کہ خدا، رسول، آخرت اور روح جیسے الفاظ کو ایک خاص صورتحال کا ردعمل مانا جائے۔ انہیں سچا کہا جائے نہ جھوٹا۔ کبھی وہ بامعنی تھے، اب بے معنی ہوچکے ہیں۔
۸۔ اسلام کی نشأۃ ثانیہ: اکیسویں صدی
اس دور میں باقی تمام چیزیں افکار و خیالات اور رجحانات بیسویں صدی کے سے ہیں۔ البتہ فرق یہ آیا ہے کہ ۱۹۸۰ء کے جہادِ افغانستان، سوویت یونین کی شکست و ریخت، کیمونزم کی ناکامی، نیوورلڈآرڈر کے اعلان اور اس کو مسلط کرنے کے لیے عالم اسلام پر امریکی یلغار کے بعد…… ایک طرف ’اسلامی نظریے‘ کی پائیداری اور دوسری طرف مغربی افکار کی بے وزنی ثابت ہوگئی ہے۔ عالم اسلام طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بھی حوصلہ مند ہے اور مغرب تمام تر وسائل جھونک کر بھی ہنوز کامیابی سے دور ہے۔
مغرب کے تیار کردہ متبادل نظامِ زندگی
فلسفے کے مختلف ادوار اور ان میں ابھرنے والے نظریات سے مغرب میں تین بڑی تحریکیں نمودار ہوئیں جن کا مدار خالص عقلیت پسندی اور مادہ پرستی پر تھا۔
۱۔ ہیومنزم یا انسان پرستی
۲۔ تحریک تنویر
۳۔ رومانیت
۱۔ انسان پرستی:(Humanism)
ہیومنزم(انسان پرستی) نے تحریک احیائے علوم کے ساتھ ساتھ جنم لیا تھا۔ ہزاروں برس سے یہ حقیقت مسلَمہ تھی کہ اولادِ آدم نوع کے لحاظ سے ’انسان‘ ہے۔ اور کائنات میں اس کی حیثیت ’بندے‘ کی ہے۔ مگر ہیومنزم کی تحریک نے انسان کے بندہ ہونے کی حیثیت کا انکار کرتے ہوئے اسے ’آزاد فرد‘ کا مقام دیا۔ انسان پرستی کا معنی ہے کائنات میں موجود چیزوں میں انسان کو سب سے اہم سمجھنا۔ اور ہر بات پر انسان کے نقطۂ نظر سے غور کرنا۔
۲۔ تحریک تنویر:(Enlightenment Movement)
انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا میں ’تحریک تنویر‘ کی درج تعریف کا خلاصہ یہ ہے:
’’یہ سترہویں اور اٹھارہویں صدی کی ایک یورپی علمی تحریک ہے جس میں خدا، عقل، فطرت اور انسان سے متعلقہ نظریات کو ایک وسیع دنیاوی نقطۂ نظر کے ساتھ اس طرح پیش کرنا ہے جو آرٹ، فلسفے اور سیاسیات میں انقلابی ترقی کا باعث ہو۔ تحریک تنویر کے نظریات کے مطابق جو آدمی کائنات کو سمجھنا اور اپنی حالت کو بہتر بنانا چاہتا ہے وہ عقل پر انحصار کرے۔ عقلیت پسند انسان، معلومات، آزادی اور خوشی کے حصول کی کوشش کرتا رہتا ہے۔‘‘
تحریک تنویر کے نزدیک انسانی عقل تین ذرائع استعمال کرکے اصل حقائق تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ ذرائع ہیں: استقراء، استخراج اور وجدان۔ ’استقراء‘ کا معنی ہے جزئیات کے مشاہدے کے ذریعے کوئی قانون اخذ کرنا۔ ’استخراج‘ کا مطلب ہے ایک قاعدہ کلیہ سوچ کر اسے جزئیات پر منطبق کرکے حقیقت کا پتہ چلانا۔ ’وجدان‘ کا مطلب طبعی احساسات کے ذریعے کسی شے کے اچھے برے ہونے کا فیصلہ کرنا۔ پس مذہبی رہنمائی کی قطعاً ضرورت نہیں رہ جاتی۔
۳۔ رومانیت (Romanticism)
انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا میں رومانیت کی تعریف اس طرح کی گئی ہے:
’’یہ اٹھارہویں سے انیسویں صدی کے وسط تک مغربی معاشرے کو متاثر کرنے والا ایک عملی رجحان ہے جس نے ادب، مصوری، موسیقی، فن تعمیر، تنقید اور تاریخ نویسی پر گہرے اثرات چھوڑے۔‘‘
’تحریک رومانیت‘ بھی حواس خمسہ، عقل اور وجدان کو علم کا اصل ذریعہ سمجھتی تھی اور کسی خارجی ذریعۂ علم کی قائل نہیں تھی۔
ان تحریکوں کے اثر سے یہ طے ہوچکا تھا کہ انسان کی خواہش اور پسند ہی اچھے، برے کا معیار ہے اس لیے ایک آئیڈیل معاشرہ تشکیل دینے کے لیے بھی انسانی خواہش ہی کو محور بنایا گیا۔ یہ بھی تسلیم کرلیا گیا کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش آزادی ہے، یعنی انسان جو کچھ چاہے اسے حاصل کرسکے۔ انسان کی ترقی بھی اسی آزادی پر موقوف ہے۔ اب رہی یہ بات کہ انسان کی آزادی کس حد تک ہو اور کس انداز کی ہو؟ اس بارے میں مفکرین اور فلاسفروں میں اختلاف ہوا، اس طرح کئی نظامِ زندگی اختراع کیے گئے جن میں سیکولرازم، لبرل ازم اور کیمونیٹیرین ازم زیادہ اہم ہیں۔ یہ سب نظام اس بات پر متفق تھے کہ ’آزادیٔ فرد‘ افضل ترین مقصد ہے تاکہ جو چاہے وہ حاصل کرسکے۔ اسی طرح یہ تینوں مذہب کے انکار، خالص عقلیت پسندی اور انسان پرستی پر بھی متفق ہیں۔ بس طریقہ کار میں اختلاف تھا۔
اب ہم ان ازموں کا مرحلہ وار جائزہ لیں گے۔
سیکولر ازم:
سیکولر ازم انسانی زندگی کو دو الگ حصوں میں بانٹتا ہے؛ ذاتی زندگی، سماجی زندگی۔ ذاتی زندگی میں انسان مذہب پر عمل کرنا چاہے تو کرسکتا ہے۔ دوسرا حصہ سماجی زندگی کا ہے، اس میں مذہب کی مداخلت بالکل نہیں ہوگی بلکہ عقل بالاتر رہے گی۔
لبرل ازم:
لبرل ازم تین اصولوں پر قائم ہے…… ۱۔ آزادی ۲۔ مساوات ۳۔ عدل
آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی آزادی اور من مانی کا انفرادی طور پر اظہار کرسکتا ہے۔ مگر چونکہ اس قدر آزادی سے دوسروں کی زندگی میں خلل پڑ سکتا ہے اس لیے زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کرلیا جائے؛ پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف۔ پبلک لائف میں انسان ضروری معاشرتی پابندیوں کا لحاظ کرے اور پرائیوٹ لائف میں جو چاہے کرے۔ شراب پیے، بدفعلی کرے یا خدا کی عبادت کرے اس کی مرضی۔
مساوات سے یہ مراد ہے کہ انسان قانونی اور سیاسی طور پر برابر ہیں۔ قانونی طور پر اس طرح کہ قانون ہر شخص کو نجی زندگی میں کچھ بھی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سیاسی طورپر مساوات اس طرح کہ ہر شخص کا ووٹ برابر ہے۔
لبرل ازم میں عدل کے تصور سے یہ مراد ہے کہ ہر انسان کے اہداف کو معاشرے میں یکساں احترام حاصل ہوگا چاہے وہ شفا خانہ قائم کرنے کا ہدف ہو یا قحبہ خانہ کھولنے کا۔
کیمونیٹیرین ازم:
اس کے بانی روسوہیگل اور مارکس تھے۔ ان کے نزدیک ہر انسان انفرادی طور پر خیر اور شر کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا فیصلہ انسانوں کی مجموعی اغراض کو دیکھ کر کرنا چاہیے۔ اس طرح کیمونیٹیرین ازم سے انسان کی آزادی کا اجتماعی تصور پیدا ہوا۔
آگے چل کر یہ نظریہ کئی شاخوں میں بٹ گیا۔ جن میں سے دو اہم ترین ہیں:
۱۔ قوم پرستی (Nationalism)
۲۔ اشتراکیت (Socialism)
۱۔ قوم پرستی (Nationalism)
قوم پرستی یہ کہتی ہے کہ انسانوں کو اپنی اجتماعی آزادی کا اظہار قومی حیثیت سے کرنا چاہیے۔ اب چونکہ قومیں کبھی نسلی بنیاد پر بنتی ہیں اور کبھی وطنی بنیاد پر، اس لیے قوم پرستی کی دو شکلیں بن گئیں۔
۱۔ وطنی قوم پرستی(Civil Grounded Nationalism)
اس نظریے میں لوگ کسی ریاست کے شہری ہونے کی حیثیت سے ایک قوم شمار ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد اپنی قوم کے لیے زیادہ سے زیادہ آزادی، قوت اور وسائل جمع کرنا ہوتا ہے۔
۲۔ نسلی قوم پرستی(Ethical/Racial ground Nationalism)
اس نظریے میں لوگ کسی نسل سے تعلق کی بناء پر ایک قوم مانے جاتے ہیں۔
گزشتہ صدی میں ہٹلر نازی ازم قوم پرستی کا علمبردار تھا اور مسولینی کا فاشزم وطن پرستی کا علمبردار تھا۔
۲۔ اشتراکیت: (Socialism)
اشتراکیت یہ کہتی ہے کہ انسانوں کا اصل نمائندہ طبقہ مزدور لوگ ہیں۔ انہیں کی اغراض اور خواہشات کو انسانوں کی اغراض مان کر معاشرے کا نظام بنایا اور چلایا جائے۔اشتراکیت اور قوم پرستی کی تمام قسمیں، کیمونیٹیرین ازم کی شاخیں ہیں۔ لبرل ازم کیمونیٹیرین ازم کا بھائی ہے۔ یہ نظریات اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے کیونکہ ان کا مقصد صرف دنیاداری، مفادپرستی اور اتباعِ ہوا ہے۔ یہ نظام آزادی، مساوات، عدل اور ترقی کا جو معیار پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے جو راہ اختیار کرتے ہیں، اس کا پہلا قدم ہی انسان کو مذہب سے منحرف کردیتا ہے۔
(جاری ہے، ان شاء اللہ)